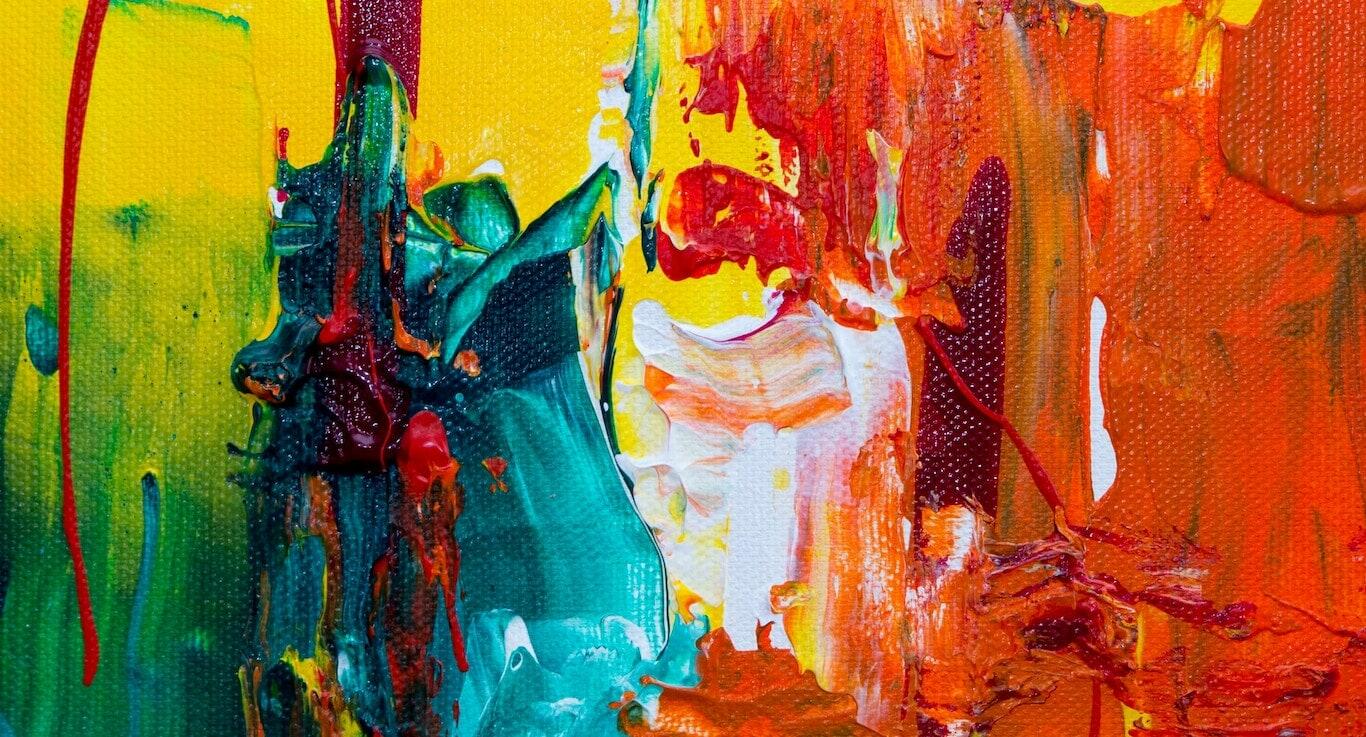محمد حسن کا تنقیدی وِژن
(’’دہلی میں اردو شاعری کا تہذیبی وفکری پس منظر‘‘کی روشنی میں)
پروفیسرمحمد حسن جتنے بڑے محقق تھے اتنے ہی بڑے تخلیق کار اور ناقد بھی۔تحقیق ،تنقیداورتخلیق کااتنا گہراامتزاج اردو ادب میں کم ہی نظر آتا ہے۔انھوں نے اپنی شخصیت کوکسی ایک خانے یاچوکھٹے میں قید نہیں رکھا،یہ ان کی ہمہ جہت شخصیت کی روشن علامتیں ہیں جن کی وجہ سے محمدحسن ادب کا نیّرِ اعظم بن گئے۔ مارکسیت ان کی کمزوری ضرور تھی مگرانہوں نے آنکھ بند کرکے تنقید کے کسی بھی نظریہ کو اختیار نہیں کیا ہے۔ وہ کھلے ذہن کے انسان تھے اور ادب کے بدلتے رویے اور رجحانات پر ان کی نظر گہری تھی۔ انھوں نے اپنی تنقید کی اساس گہرے مطالعہ پر رکھی تھی اس لیے وہ ادب کے تجربہ میں عام نقادوں کی روش سے مختلف راہ اپناتے تھے۔ وہ سائنسی طریق کار کے قائل تھے اس لیے ادب کا جائزہ سائنسی طریقہ سے لیتے تھے ۔محمد حسن کا خیال ہے کہ ادب کے عروج وزوال میں تہذیبی اورسماجی عوامل کارفرما رہتے ہیں لہٰذا اس کے عروج وزوال کے وجوہات کی تلاش تہذیبی اورسماجی عوامل کی روشنی میں کرتے ہیں۔ان کا خیال ہے کہ تخلیقی عمل پیچیدہ عمل ہے اور اس عمل کے دوران بعض عوامل خاموشی سے اثرانداز ہوتے ہیں جنہیں تعین قدر کے وقت نظرانداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔انہوں نے لکھا ہے
’’تخلیق دراصل تین سطحوں سے ہوکر گزرتی ہے وہ اپنے مصنف کی ذات کا اظہار بھی ہوتی ہے۔اس کے عصری شعور کی آواز بھی اوراس دورسے پیداہونے والی آفاقی اقدارکی گونج بھی۔اس لیے ہردورکے سنجیدہ ادب کامطالعہ لازمی طورپرمصنف کامطالعہ(تحقیق،سیرت اورنفسیات کی مدد)عصرکامطالعہ (عمرانیات، اقتصادیات اور سماجی علوم سے)اورآفاقی اقدار کا مطالعہ جمالیات اورتاریخ کی مدد سے بن جاتا ہے۔‘‘ )آج کل،جولائی 2010 ، ص- 11-12 (
ان خیالات کااظہار ان کی مشہور کتاب’’دہلی میں اردو شاعری کا تہذیبی وفکری پس منظر‘‘ میں تفصیل سے ہواہے،جوکہ ان کی تحقیقی اور تنقیدی بصیرت کی عمدہ مثال ہے، جس میں انہوں نے تہذی یا اقتصادی عوامل کی روشنی میں ادب کو پرکھنے کی ترغیب دی ہے ۔اس کتاب میں بعض جگہ مارکسی تنقید کی جھلک بھی ملتی ہے لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پوری طرح سے مارکسی تنقید کے حامی تھے۔لیکن یہ حقیقت ہے کہ متذکرہ کتاب کے شائع ہونے کے بعد ادب کامطالعہ تہذیب کی روشنی میں کرنے کی ضرورت پر زور دیا جانے لگا اورمختلف اصناف کا اب تک نہ جانے کتنے تہذیبی مطالعات پیش کیے جا چکے ہیں اور ہنوزکیے جارہے ہیں۔
اردوزبان وادب کے متعلق محمدحسن کاخیال ہے کہ یہ ہند آریائی دو تہذیبوں کا سنگم ہے ۔لیکن انہوں نے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ان دونوں تہذیبوں کو ہندو اور مسلم تہذیبوں سے منسوب نہیں کیا جا سکتا کیوں کہ مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہر ملک کی تہذیب ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے ۔اس لیے دنیا کے تمام مسلمانوں کے عقائد میںیکسانیت کے باوجود ان کی تہذیب مختلف ہے۔اس لیے یہ کہنا زیادہ درست ہوگاکہ اردو کا فروغ ہندوستانی اور ترک ایرانی تہذیب کے اختلاط سے ہوا اور یہ دونوں تہذیبیں آریائی تہذیبیں تھیںجن میں نسلی مناسبت تھی اور ان میں مشترک اقدار کا ذخیرہ بھی موجود تھا۔محمد حسن کا خیال ہے کہ ان تہذیبوںکے عقائد اوراقدارکے اثرات ہمارے شاعروں اور ادیبوں نے بھلے ہی قبول نہ کئے ہوں لیکن ان کے مزاج اور کردار کی تشکیل میں یہ روایات ضرور موجود رہی ہوں گی۔ اسی لئے محمد حسن نے ادب کا مطالعہ وسیع تر تہذیبی پس منظر میں کرنے پر زور دیا ہے کیوں کہ تہذیبی مطالعہ کے ذریعہ نسلی وراثت، معاشرت اور اس کی اقدار،معتقدات اورفلسفے، تاریخ اور سیاسیات ،اقتصادیات وغیرہ کے مطالعہ میں مدد ملتی ہے۔
محمد حسن کے مطابق اردو زبان ہند آریائی عناصر کی پروردہ ہے۔ محمدحسین آزاد کی کتاب’’سخن دانِ فارس‘‘ اور ’’دیباچۂ آبِ حیات‘‘ کے حوالے سے انہوں نے قدیم فارسی اور سنسکرت کو مماثل قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں نے عربی پر قدیم فارسی کی اصطلاحوں کو ترجیح دی ہے کیوں کہ یہ اصطلاحیں آریائی تھیں۔یہی وجہ ہے کہ اردو میں عربی لفظ صلواۃ کی جگہ عبادت، صوم کی جگہ روزہ، اﷲکی جگہ خدا، ملائکہ کی جگہ فرشتے اور جنت کی جگہ بہشت کہا اور لکھا جانے لگا۔ انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اردو ادب کے مزاج اور تہذیبی فضا نے قدیم فارسی کی اصطلاحوں کو ہی نہیں بلکہ تصورات، اقدار اورتہذیبی رویّوں کو بھی اپنے اندر جذب کرلیا جس کا فطری اظہار تصوف کے آئینہ میں کیا گیا۔اس لیے اردوکی صوفیانہ شاعری میں جوآزاد خیالی، وسیع المشربی اور رواداری پائی جاتی ہے یہ دراصل ایرانی اور ہندوستانی تصوف کے مشترکہ اقدار کی دین ہے۔
محمد حسن نے خانقاہوں کے سماجی رابطے،عوام پر ان کے اثرات اور تصوف کے بنیادی نظریات کو سمجھنے پرزوردیاہے کیوں کہ انہیں سمجھے بغیر اردو شاعری کی اصطلاحوں اوراس کے سماجی مفہوم کوسمجھناممکن نہیں ہے۔لہٰذاانہوں نے تصوف کے فکری ماخذوں اور اس کی اصطلاحوں کی وضاحت مختلف مبصرین اور محققین مثلاً نکلسن،دوزی،وان کریمر،براؤن اور برنارڈ شا کے علاوہ مجددالف ثانی،شاہ ولی اﷲ،ذوالنون مصری،جنید بغدادی اور علامہ اقبال وغیرہ کے نظریات سے بحث کرتے ہوئے یونانی،نوافلاطونی،ویدانتی،بدھ مت کے فلسفے اور اسلامی تصوف کے نکات پر جس طرح عالمانہ روشنی ڈالی ہے اورصوفی تحریک کی نشوونما میںایران اور آریائی نسل سے گہراتعلق رکھنے والے عالموں اورمفکروں کی خدمات کو اوّلیت دی ہے ،اس سے ان کے تحقیقی اور تنقیدی وژن کا اندازہ ہوتا ہے۔انہوں نے تصوف کی نشوونما میں شریعت اورطریقت کے نظریوں کو زیربحث لاکر تصوف کی اصل روح تک رسائی حاصل کی اور اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ تصوف کی کن خوبیوں کی بناپر عوام سے اس کا گہرارشتہ قائم ہوا۔انہوںنے عوام اور صوفیوں کے درمیان کے رشتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ صوفیوں نے اپنے افکارونظریات کوعوام کی زبان میں عوام تک پہنچانے کی کوشش کی جس سے اردوکے رسائل وجرایداوران کی تصنیفات نظم ونثرکی صورت میں شائع ہوئیں۔انہیں صوفیوں کے بنیادی افکار ونظریات کی وجہ سے اردوغزل میں آزادخیالی،وسیع المشربی کی روایت عام ہوئی۔صوفیوں نے معرفت کے منازل ومراحل کے اظہارکے لیے جن اصطلاحوں کووضع کیا وہ سب اردوغزل میں استعمال ہونے لگیں۔اردوغزل میں ایثاروقربانی ،خود فراموشی اور عشق ومحبت کے جوپاک جذبات پائے جاتے ہیں وہ بھی تصوف کی ہی دین ہیں۔ان تمام وجوہات کی بناپرمحمدحسن نے لکھا ہے
’’تصوف نے اردو شاعری کے لیے فکری سطح پر مدنی مرکزیت کی وہ بنیاد فراہم کردی جس پر ہندوستانی اور مغربی اور وسط ایشیائی معاشرے اور افکارواقداراشتراک تلاش کرسکتے تھے اور نئی تہذیب کا فکری جواز پاسکتے تھے۔‘‘
(دہلی میں اردو شاعری کا تہذیبی وفکری پس منظر،ص- 48)
وسط ایشیا کے مختلف قبیلوں کے ہندوستان اورایران آنے اورایک دوسرے کی تہذیب وروایت اوراقدار کے اثرات قبول کرنے نیزموہن جوداڑواورہڑپا کی تہذیبوں کی نشوونما کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے محمد حسن نے اسیریا،بابل اورستھین تہذیبوں سے اس کی مماثلت پر زور دیا ہے اور اسے مدلل بنانے کے لیے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ شیوکی تین آنکھوں اور ان کے کاندھوں پر سانپ کا جو تصور ہے وہ وسط ایشیا کے مشہور شہنشاہ ضحاک سے مماثلت رکھتا ہے کیوں کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ ضحاک کے شانوں پربھی سانپ اُگ آئے تھے۔ انہوں نے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ قدیم ایرانی اور قدیم سنسکرت کے متعددالفاظ اور تصورات مشترک ہیں جو دونوں تہذیبوں کی مماثلت کی دلیل ہیں۔
محمد حسن نے اردو زبان کو کھچڑی زبان سے تعبیر کیا ہے اوراس کے وجود میں آنے کی تاریخی وجوہات پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک مورّخ کی طرح عرب تاجروں اور حکمرانوں کے ورودہندوستان اوراستحکام حکومت کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور وضاحت کی ہے کہ تجارتی کاروبار کوہندوستان سے مغربی ایشیا، یوروپ اور بحرروم تک پھیلانے کی کوشش میں کس طرح ایک کھچڑی زبان وجود میں آئی اور ہندوستان میں مختلف علاقائی زبان ہونے کے باوجود کس طرح اس کھچڑی زبان کو مرکزیت حاصل ہوئی جوبعد میں لسانی،فکری اور تہذیبی حیثیت اختیا رکرنے لگی۔انہوں نے ان نکا ت کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے اشارہ کیا ہے کہ یہی زبان مختلف حکمرانوں سے ہوتی ہوئی مغلوں کے دورحکومت میں پہنچی ۔ اس زمانے میں برج،اودھی،راجستھانی اور ناگراپ بھرنش جیسی بولیاں بولی جاتی تھیں یہ بولیاں ایک مرکزی بولی کوجگہ دینے لگی تھیں جسے ہندوی کہاجانے لگا تھا۔اس ہندوی زبان کی نشانیاں اس وقت کے ایک مشہور صوفی شاعر امیر خسرو کے کلام میں ملنے لگی تھیں۔
محمدحسن نے اکبراعظم سے قبل اور بعدکی مدنی مرکزیت کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اس دور کے دوسرے صوفی شعرا اورمفکرین مثلاً کبیر،نانک، نام دیو اور جائسی وغیرہ نے ایک مشترکہ روایت کی تصویر پیش کی اور افتراق کی جگہ اشتراک کی فکری بنیادیںتلاش کیںکیوں کہ اس وقت ایک ایسے فکری نظام کی ضرورت تھی جومدنی مراکزمیں رہنے والوں کے درمیان’’ جیواورجینے دو‘‘کی بنیاد بن سکے اور ان میں اپنائیت پیدا کرسکے۔محمد حسن نے مذکورہ بالا شعرا اور مفکرین کی ’’جیواورجینے دو‘‘کے فلسفۂ فکر کی روشنی میں بھکتی اور اسلامی تصوف کو مذہب کی ظاہری رسم پرستی پر ترجیح دی ہے اور یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ اردو زبان وادب پر بھکتی اور تصوف کے افکار کے اثرات کس طرح مرتب ہوئے ۔
ہندوستان کی مدنی مرکزیت کی شکست وریخت کا جائزہ پیش کرتے ہوئے محمد حسن نے مغلوں کے دورِحکومت میں ایسٹ انڈیاکمپنی کی آمد،مغل دربارمیں اپنا اثرورسوخ بڑھانے اور مغل شہزادے وشہزادیوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ مل کرتجارت کرنے اور پھر رفتہ رفتہ ہندوستان پر انگریزوں کے قابض ہونے کی تفصیل جس طرح بیان کی اور تمام حالات کا جائزہ لیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تاریخی شعور نہایت بالیدہ تھا اور سیاسی شعور میں بھی پختگی تھی۔محمد حسن نے بڑی تفصیل سے اس زمانے کے سیاسی،سماجی اور معاشی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کی دولت لُٹ رہی تھی،یہاں کا تجارتی نظام درہم برہم ہورہاتھا لیکن یوروپ کی معاشی حالت بہتر سے بہتر ہورہی تھی، ان کا نظام حکومت اورتجارت مستحکم اور مضبوط ہورہا تھا۔مغل حکومت کی گرفت تیزی سے کمزورہونے لگی تھی،لٹیرے اور حملہ آور ہندوستان کے اہم مراکز پرحملے کرنے لگے تھے۔چاروں طرف قتل وغارت ، لوٹ مار اورافراتفری کاماحول تھا۔ان تمام وجوہات کی بناپرہندوستان کی مدنی مرکزیت ختم ہونے لگی تھی۔یہاں کے شاعروادیب اور دیگر فنکار معاشی بدحالی کا شکارہوگئے تھے۔وہ سرپرستوں اور چھوٹے چھوٹے درباروں کی تلاش میں بھٹکنے پر مجبور ہوگئے تھے۔شعرا اور ادیب اپنی جڑوں سے کٹنے لگے اور خودکوبے سروسامان اورتنہا محسوس کرنے لگے۔ان کی شاعری میں اجتماعیت کے بجائے انفرادیت کی آواز سنائی دینے لگی۔رفتہ رفتہ ہندوستان کی تہذیبیں بھی منتشر ہونے لگیں اور شاعری کا مزاج بھی بدلنے لگا۔
محمد حسن نے اس دور یعنی 18 ویں صدی کی شاعری کوتین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔’’پہلاحصہ مدنی مرکزیت کی اس تلاش سے متعلق ہے جوفکری سطح پر ہورہی تھی جس کاسرچشمہ ہندوستانی،ایرانی اور اسلامی تصوف تھا۔اس ضمن میںانہوں نے موت کے تصوّر کی تین صورتوں کی وضاحت کی ہے جس میں پہلی شکل کے متعلق ان کا خیال ہے کہ یہ تبدیلی کی خواہش ہے جوہر طرح کی تکلیف سے نجات دلا سکتی ہے،تسلی کی صورت پیدا کرکے زندگی کے زخم بھرسکتی ہے۔دوسری صورت کوعدم مساوات اور سماجی بے انصافی کودورکرنے سے تعبیرکیا ہے جو غریب اور امیر کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کرتی ہے۔تیسراوحدت الوجودی تصور ہے جس کے مطابق انسان مرنے کے بعد خالقِ مطلق سے مل جاتا ہے۔انہوںنے ان تینوں صورتوںپر جس طرح روشنی ڈالی ہے اس سے موت کاتصور ایک تخلیقی سرچشمے کی صورت میں ابھرتاہے جس میں زندگی کی نئی توانائیوں کی بشارت ملتی ہے۔ان کا خیال ہے کہ موت کے اس تصور سے انسان دولت وکامیابی،اقتداروقوت کے نشے سے بیدار ہوجاتا ہے اور دکھ دردکوعیش ونشاط پراورخاکساری وکم مائگی کوغروروتکبّر پرترجیح دیتاہے۔محمد حسن نے ان خیالات کی نشاندہی اس دور کی شاعری میں کی ہے۔
دوسرے حصہ میں محمدحسن نے تہذیبی سطح پر مدنی مر کزیت کی تلاش کی ہے جس میں افراد اور معاشرہ کا تذکرہ کیا ہے ۔اس سلسلے میںانہوں نے ہندوستانی سماج کی خصوصیت پرتبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سماج مختلف ادوارمیں کئی چھوٹی چھوٹی دیہی ، قصباتی اور علاقائی وحدتوں میں منقسم رہاتھا جو اپنی انتظامی اوراقتصادی ضرورتیں خود پوری کرلیتی تھیں اور ساتھ ہی ان کی لسانی اور ادبی انفرادیت بھی قائم رہتی تھی اور کبھی کبھی مذہبی اور تہذیبی بھی ۔لیکن بکھری ہوئی ان اکائیوںکوکسی ایک وحدت میں ضم کرنے کوشش ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔انہوںنے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ یہ کوشش ایک طرف ہندوستان گیرمدنی مرکزیت کی تعمیروتشکیل کی کوشش تھی تودوسری طرف مغربی اوروسط ایشیائی تہذیبی وحدت سے ہم آہنگ کرنے کی بھی کوشش تھی۔اس بناپر انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس کوشش سے ایک ایسی تہذیب اور ایک ایسا ادب وجود میں آیا جس میں علاقائی رنگ بھی تھااورہندوستان گیر اورمغربی اوروسط ایشیائی تہذیب کارنگ وآہنگ بھی تھا۔لیکن جیسے جیسے ہندوستان گیراورعالم گیر تہذیب کارنگ گہرا ہوتا گیا ویسے ویسے علاقائی وحدتوں کا خودکفالتی اندازبکھرتااور ٹوٹتا چلاگیا۔اس لیے اس دور کی شاعری میں معاشرے کی جگہ فردکی آواز ابھرنے لگی جس کی مثالیں ولی کی شاعری میں سب سے زیادہ موجود ہیں۔
محمدحسن نے تیسرے حصہ کو ادب کی سطح پر مدنی مرکزیت کی تلاش سے تعبیر کیا ہے جس میں ایک طرف ہندوستانی اور ایرانی عناصر کی کشمکش پرروشنی ڈالی ہے تو دوسری طرف ہندی اور فارسی اثرات کی آمیزش کی طرف اشارہ کیاہے توتیسری طرف دکنی اور دہلی کے ادبی ملاپ کا تذکرہ کیا ہے۔ہندوستانی اور ایرانی عناصر کی کشمکش کے متعلق ان کا خیال ہے کہ اورنگ زیب کی وفات(1707 ء) کے پندرہ سال کے اندر ہی دہلی کے ادبی مذاق میں تبدیلی آنے لگی تھی اورفارسی شاعری کے ساتھ ساتھ ریختہ گوئی کی بھی شروعات ہوگئی تھی۔انہوں نے اس ادبی انقلاب کے رونما ہونے میں جو سماجی،سیاسی اورمعاشی وجوہات کارفرما تھیں ان پر بھی روشنی ڈالی ہے۔اس سلسلے میں ان کا خیال ہے کہ ادبی انقلابات نئے تقاضوں کی بناپررونماہوتے ہیں اور ان تقاضوں کی گونج بیک وقت سیاست سے لے کر تہذیب ومعاشرت تک سبھی شعبوں میں سنائی دیتی ہے۔محمد حسن کی تحقیق کے مطابق اس دور کا نظام ذرائع پیداوار کی راہ میں رکاوٹ بننے لگا اور سماج کا بڑاحصہ زندگی کی عام ضروریات سے محروم ہونے لگا تھااس لیے ایک ایسا طبقہ وجودمیں آیا جو نظام حکومت سے نئے مطالبے کرنے لگا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب امراکازوال ہونے لگا تھا اور ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے اجارہ داروں کاعروج بھی ہونے لگا۔اپنے علاقے اور زمین سے ان اجارہ دار وں کا تعلق اس وقت کے بڑے بڑے امرا جو ایرانی اور تورانی جماعت میں منقسم تھے کے مقابلے میں زیادہ گہرا تھا۔اس لئے چھوٹے درباروں میں فارسی شعرا کا غلبہ نہیں تھا بلکہ ہندوستانیت زیادہ اور ایرانیت کم تھی۔اسی زمانے میں زراعتی بدحالی کی وجہ سے کسان نوکریوں کی تلاش میں دیہاتوں سے شہروں اور خاص کر دہلی کی طرف منتقل ہونے لگے جس کا اثر دہلی کی تہذیبی اور ادبی رجحان پر بھی پڑا۔اس لیے محمدحسن نے عام تصور کے برخلاف یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اردو شاعری کا رواج امرا کی قدردانی اور دربار شاہی کی سرپرستی کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ یہ عظیم تہذیبی رو ایت کا مظہر تھا۔لہٰذا شمالی ہندوستان میں اردو ادب کی ابتدافارسی اورہندی کی مشترکہ روایات کے زیراثر ہوئی ہے۔ابتدا ئی دور سے اردو ادب کے نشونما میں دونوں روایات اثرانداز ہوتی رہی ہیں۔ ہندی عناصر کی تشکیل مختلف بولیوں اورزبانوں مثلاً کھڑی بولی،برج بھاشا،اودھی، میتھلی اورراجستھانی وغیرہ سے ہوئی ہے۔محمد حسن نے تذکرۂ چمنستان شعرا سے کئی اشعار نقل کیے ہیں جن میں فارسی شعرا کے اثرات موجود ہیں۔ہندی کے سلسلے میں ان کاخیال ہے کہ سنسکرت کے قصے کہانیاں،اخلاقی تمثیلیں،مذہبی روایات اورفلسفیانہ تصانیف کے ترجمے جو عربی اور فارسی میں ہوئے تھے، ان کے اثرات اردو ادب میں بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔انہوں نے مزید وضاحت کی ہے کہ اردوادب پر ہندی کے اثرات بھکتی کال کی شاعری کے ذریعہ مرتب ہوئے۔ مختصر یہ کہ اردو ادب نے جہاں فارسی ادب سے حسن کاری، لفظوں کے دروبست،اضافت اور تراکیب، شاعرانہ لب ولہجہ اورشائستگی وشستگی کا تصور لیا وہیں ہندی شاعری سے بالواسطہ کئی چیزیں مثلاً تمثیلی پیرایۂ اظہار،عشق کے بعض تصورات، صنعت گری اور نک سک اور نائکہ بھید کے رموزسیکھے۔ہندی کے اثرات محمدشاہی دور کی اردو شاعری میں دیکھے جاسکتے ہیں۔
دکنی اور د ہلی کی ادبی وراثت کے ملاپ کاتذکرہ کرتے ہوئے محمد حسن نے وضاحت کی ہے کہ کس طرح دہلی میں اردو شاعری کاچرچا ولی کے کلام کے دہلی آنے کے بعد سے ہوااورکس طرح اس کے زیراثرریختہ گوئی کی طرف شعراکا ذہن مبذول ہوا۔انہوں نے دکنی ادب کے نشوونما اورپختگی حاصل کرنے کے محرکات کاجائزہ لیا اور یہ بتایاکہ دکنی ادب نے کس طرح فارسی ادب کے آب ورنگ اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت پیداکی۔نیزانہوں نے ان اقدار کی طرف اشارہ کیا ہے جودکنی ادب کے ساتھ دہلی آئے اور اردو شاعری کے پیکر میں سما گئے۔ دکنی شاعری نے گجراتی،بیجاپور،گول کنڈہ اوردورمغلیہ کے دکنی شعرا کے کلام سے جوذخائر حاصل کیے تھے، ان کاجائزہ لیتے ہوئے محمدحسن نے اظہارخیال کیاہے کہ دکنی شاعری اسلوب کے اعتبار سے مربوط تھی اوران میں مذہبی،رزمیہ اوررومانی عناصرکی افراط تھی اور ان میں مقامی رنگ کاغلبہ بھی تھا۔نیز ان نظموں،تمثیلوں،مثنویوں اورقصیدوںمیں کہیں اخلاقی اورمذہبی نصیحتیں ملتی ہیں تو کہیں وارداتِ حسن وعشق اور کہیں موسموں کابیان ہے تو کہیں تقاریب کی سجاوٹیں۔اس لیے انہیںغزل پر فوقیت حاصل ہے۔محمد حسن کاخیال ہے کہ بھلے ہی دکنی شاعری کی یہ خوبیاں ولی کی شاعری میں پورے آب وتاب کے ساتھ موجود نہ ہوں لیکن دہلی کی شاعری میں ان کے ارتعاشات موجود ہیں۔
محمدحسن نے محمد شاہ اور شاہ عالم کے دور میں ہندوستان کی بحرانی صورت حال کا جائزہ پیش کرتے ہوئے ان تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہندوستان میں تاتاریوں کے قتل عام کے بعد بغداداورایران کی تاریخی صورتِ حال اپنے آپ کودہرارہی تھی۔ چنگیزخان اورہلاکونے وہاں کی حکومت اور تہذیب کی بنیادیں ہلادی تھیںاور ہندوستان میں نادرشاہ،احمد شاہ ابدالی،غلام قادراورروہیلوں نے دہلی میں قتل وغارت کرکے یہاں کی سیاسی اورتہذیبی مرکزیت ختم کردی تھی جس سے دہلی میں انتشار،ابتری،بے یقینی اور حال کی بے اعتباری کا احساس عام ہونے لگا تھا ۔اس لیے اس دور کی شاعری میں دنیا کی رنگینی اور اس کی بے ثباتی کے ارتعاشات موجود ہیں ۔محمد حسن نے ان کی مثالیںحاتم، میر تقی میر،خواجہ میردرداورسودا کی شاعری میںتلاش کی ہیں۔
محمدحسن نے دہلی کی شاعری میں صنعت ایہام گوئی اوراس کے عروج وزوال پر تفصیل سے گفتگوکی ہے اور عربی،فارسی اور ہندی سے مثالیں بھی دی ہیں۔انہوں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ صنعتِ ایہام گوئی کی روایت ہزاروں سال پرانی ہے۔سنسکرت میں اس صنعت کو ’’شلیش‘‘کہاجاتاتھا۔انہوں نے شلیش کی مثالیں کالی داس کی شاعری میں بھی تلاش کی ہیں۔ ایہام گوئی کے فائدے اور نقصانات پر اظہار خیال کرتے ہوئے اشارہ کیا ہے کہ کس طرح اس صنعت سے متاثر ہوکر شعرا نے الفاظ کے پیکر تراشے اور اردو کے دامن کوعربی،فارسی اورہندی الفاظ ومحاوروں سے مالامال کردیا ۔انہوں نے دہلی کی شاعری کا جائزہ لینے کے بعد اس نکتے کی بھی وضاحت کی ہے کہ اس دور کی شاعری اجتماعی زندگی سے برسرِ پیکارشخصیتوں کی شاعری نہیں ہے بلکہ اجتماعی زندگی سے ہم آہنگ شخصیتوں کی شاعری ہے۔لہٰذااس دورکی شاعری کامزاج داخلی اورانفرادی ہونے سے زیادہ اجتماعی اورمجلسی ہے۔تصوّرات اورخواب اس دورکے مذاق کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں جنہیں شعراخوش مذاقی اورصنعت گری کے ساتھ پیش کرتے تھے۔اس دورکے مذاق کے مطابق شعرانے زندگی کے نشاط کوبے جھجک پیش کرتے تھے اوراپنے معاشقوں ،معاملہ بندی اورامرد پرستی کاذکر اورسراپانگاری کرتے ہوئے نہیں شرماتے تھے۔اس لیے اس دورکی شاعری میں سوزوگدازکی کمی ہونے کے باوجود سچی شعریت کے عناصرموجود ہیں۔ محمد حسن کاخیال ہے کہ اس دور یعنی اٹھارہوی صدی کی شاعری ایک تاریخی،جذباتی اور تہذیبی ضرورت کوپورا کررہی تھی اورنئے درمیانی طبقے کے لیے سرمایۂ تسکیں اور اظہار کا ذریعہ تھی اور جودربار سے الگ ہٹ کر ایک ایسی تہذیب کی نشوونما کررہی تھی جوہندوستانی ہونے کے باوجود ایرانی تہذیب کی شائستگی اور لطافت اپنے اندر سموئے ہوئی تھی۔
محمد حسن نے دہلی کی اردو شاعری کا جوتہذیبی اورفکری پس منظرپیش کیاہے وہ ان کی وسعت مطالعہ اورتحقیقی وتنقیدی بصیرت کی مثال ہے۔انہوں نے تہذیبی ، سماجی،سیاسی، معاشی اورفکری پس منظر میں ادب کی تفہیم و تنقید کی اہمیت پر زور دیا ہے اس کااطلاق دنیا کے تمام ادبیات پربھی کیا جاسکتاہے۔دنیا کے کسی بھی ملک کا ایسا کوئی ادب نہیں ہے جس کے نشوونمااورعروج وزوال میں اس دور کی سماجی،سیاسی،معاشی اورتہذیبی محرکات وعوامل نے اہم رول نہ ادا کیاہو۔محمدحسن کی یہ کتاب دہلی کی اردوشاعری سے متعلق ضرور ہے مگر اس سے ادبیات عالم کی تفہیم کی راہیں بھی روشن ہوتی ہیں۔
٭٭٭٭