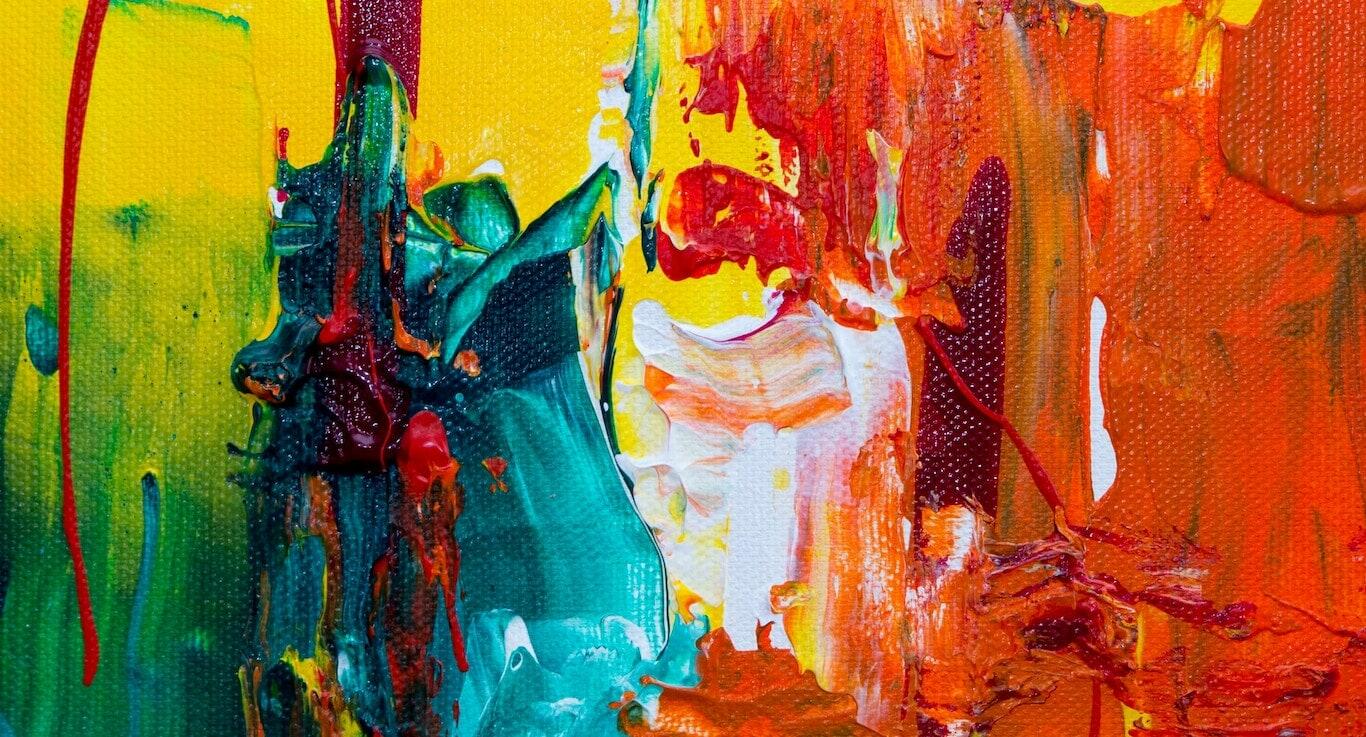بابائے جمالیات پروفیسرشکیل الرحمٰن ہندوستانی جمالیات کا تنقیدی استعارہ بن چکے ہیں۔انہوں نے ادب اور فنونِ لطیفہ کی جمالیاتی جہتوں سے اردو کے قارئین کو روشناس کرایا ہے۔’’ہندوستانی جمالیات ‘‘میںہندوستان کی ہزاروں سال پرانی تہذیبی جمالیات کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ہندوستان جمالیاتی سطح پر دیگر ممالک سے زیادہ زندہ وتابندہ نظر آتا ہے۔’’غالب اور ہند مغل جمالیات ‘‘میں غالب کی شاعری ہی نہیں بلکہ مغل دور کے فنونِ لطیفہ کی لطافت اور نزاکت پر عالمانہ جمالیاتی ڈسکورس ہے۔’’رومی کی جمالیات‘‘ اور ’’حافظ کی جمالیات ‘‘تصوّف اور روشنی کے فلسفے کی جمالیات پر محیط ہے۔
جمالیات ایک ایسی اصطلاح ہے جس کی تعریف وتوضیح پیش کرنا انتہائی مشکل کام ہے کیوں کہ اس میں اتنی تہیں اور جہتیں پائی جاتی ہیں کہ ان کی تہوں اور جہتوں کو کھولنا اور ان پر روشنی ڈالنے کا کام کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔کوئی ماہرِجمالیات اس کی تہوں کو اتنا ہی کھول سکتا ہے اور اس پر روشنی ڈال سکتا ہے جتنا اس کا مطالعہ اور مشاہدہ وسیع ہوگا۔شکیل الرحمٰن نے فیثا غورث، سقراط،ارسطو،لیونارڈ،بوآئیلو(Boileau )،بام گارٹن(Baumgarten )،ہیگل،نوالس (Novalis )،چرنی شاسکی (Chernyshoiski ) اوربلسکی (Belinsky ) وغیرہ جیسے فلسفیوں کی نظریات پرتبصرہ کرتے ہوئے جمالیات کی جو توضیح وتشریح پیش کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصطلاح کثیرالجہات صو رت میں مظاہر قدرت ہے اور سمٹی ہوئی حالت میں خدائے واحد کے مترادف ہے جس کی تعریف ،توضیح اور تشریح جتنی بھی کی جائے کم ہے۔جس طرح اس دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کا کام ابھی جاری ہے اسی طرح بقول شکیل الرحمٰن ’’ جمالیات‘‘ کی تعریف،توضیح اور تشریح کا کام ابھی جاری ہے اوراس کی معنویت پھیلتی جا رہی ہے اور اس کی نئی جہتیں مزید نمایاں ہوتی جا رہی ہیں۔
شکیل الرحمٰن کے مطابق فنون لطیفہ یا مناظر کائنات کے کسی بھی ذرّہ کے اصل جوہرکی دریافت جمالیات کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔فلسفیوں کا خیال ہے کہ کسی بھی شے کا اصل جوہر خدا ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمالیات ایک ایسا Tool ہے جس کی مدد سے خدا اور اس کی صفات کو بھی دریافت کیا جا سکتا ہے۔شکیل الرحمٰن نے تو اپنی تخلیقات میں ادب اور آرٹ کے نہ جانے کتنے ہی جواہرات دریافت کیے ہیں، لیکن افسوس کہ شکیل الرحمن کی تنقیدی جمالیات کو کما حقہ ابھی تک کسی نے دریافت نہیں کیا ہے۔شاید کم ظرف صوفیوں کی طرح ان کے نقاد بھی راہِ مقام میں ہی بھٹک جاتے ہیں۔
شکیل الرحمٰن جب بھی سنسکرت جمالیات کے جوہر مثلاً راگ راگنیوں،رس اوررسوں میں شرنگار رس،بھوں اور بھوؤں میں رتی بھو وغیرہ کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو ساتوں طبق روشن ہوجاتے ہیں۔انہوں نے عورت کے وجود کو جشن زندگی کا سرچشمہ قرار دیا ہے کیوں کہ عورت کا وجود ایک نغمہ ہے۔اسی کی وجہ سے اردو ادب کو راگ راگنیوں کی خوبصورت متحرک تصویریں حاصل ہوئی ہیں۔سات سروں میںعورت مختلف راگوں کے درمیان ابھرتی ہے۔شکیل الرحمن نے محمد قلی قطب شاہ کی شاعری کامطالعہ سنسکرت جمالیات کی روشنی میں کیا ہے اور مرکزی جمالیاتی پیکریعنی عورت کوروشنیوں،خوشبوؤں،رنگوں،راگوں اور راگنیوں کا سرچشمہ قرار دیا ہے اوریہ بھی کہا ہے کہ راگ راگنیوں کا تعلق ’وقت‘اور موسموںسے گہرا ہے،عورت ہروقت اور ہرموسم میںایک نئی میلوڈی ہے۔ اسی عورت کے جمال کی وجہ سے قلی قطب شاہ کی شاعری میںشرینگاررس یعنی جنسی لذتوں کا احساس ہوتا ہے۔شکیل الرحمٰن نے سنسکرت جمالیات کے ماہر بھرت کے ایجاد کردہ اکتالیس بھوؤں کا ذکرتے ہوئے ’’رتی بھو‘‘کی اہمیت پر زور دیا جو جنسی محبت کا شدید جذبہ ہے۔ قلی قطب شاہ کی شاعری میں جو شرینگاررس ہے وہ اسی جذبے کی دین ہے۔ قلی قطب شاہ کی شاعری میں ’سیکس‘کے تعلق سے جو لمسی اور حسی احساسات ابھرے ہیں اس سلسلے میں شکیل الرحمٰن کاخیال ہے کہ ان سے انتہائی پرکشش ’جمالیاتی‘ فینومینن خلق ہوگیا ہے جس کا تعلق کئی سطحوں پرقاری کے تجربوں اور مشاہدوںسے ہے ۔اس لیے ان تجربوں سے قاری کوجمالیاتی انبساط حاصل ہونے لگتا ہے۔
شرینگار رس کی چارمنازل یعنی ’’وکاس‘‘،’’وستار‘‘،’’اہنکار اور’’ کشوبھا‘‘ کی وضاحت کرتے ہو ئے شکیل الرحمن نے اچھی تخلیق کواس کلی سے تعبیر کیاہے جو آہستہ آہستہ پھول بنتی ہے جسے ’’وکاس ‘‘کہاجاتا ہے۔’’وکاس‘‘کے بعدپھول سے جب خوشبوپھیلنے لگتی ہے تو ’’وستار‘‘شروع ہوتاہے۔’’وستار‘‘کے بعدپھول کوجب یہ احساس ہوتاہے کہ اس کا حسن اوراس کی خوشبواپنااثردکھانے لگے ہیں تواس میں ’’اہنکار‘‘پیداہوجاتاہے جوفطری ہے۔’’وکاس اور’’وستار‘‘کے بعدایک قسم کی مستی اورسرشاری آجاتی ہے جس کی کیفیت تیز جھولا جھولنے کی مانند ہوتی ہے۔یہ شرینگاررس کی آخری منزل ہے جسے ’’کشوبھا‘‘کہا گیا ہے۔ شرینگار رس کے اس نظریہ کی روشنی میں شکیل الرحمٰن نے مرزا شوق کی مثنویوںکاجو مطالعہ پیش کیا ہے وہ قابلِ تعریف ہے اور ان کی جمالیاتی Approach کی خوبصورت مثال ہے۔ شکیل الرحمن نے مثنوی بہارعشق میںاس تجربہ کو کلی کی مانند چٹخنے سے تعبیر کیا ہے جب عاشق لبِ بام ایک خوبصورت چہرہ دیکھتا ہے۔یہ ’’وکاس‘‘کی منزل ہے۔ خوبصورت چہرہ دیکھنے کے بعد عاشق اور معشوق کے درمیان کشش محسوس ہونے،ذہنی اور نفسی تصادم، حسی کیفیات اور عشق وغیرہ کے تاثرات کو شکیل الرحمٰن نے ’’وستار‘‘کہا ہے۔عاشق اورمعشوق کے تجربے رفتہ رفتہ جب جمالیاتی تجربے بننے لگے اور معشوق کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس پر کوئی فریفتہ ہو گیا ہے تو اس منزل کو شکیل الرحمٰن نے ’’اہنکار‘‘سے اورجب دونوں کے تعلقات میں ایک خاص طرح کی مستی اور سرشاری پیدا ہوجاتی ہے تواس منزل کو’’کشوبھا‘‘سے تعبیرکیاہے۔ شکیل الرحمٰن نے اس مثنوی کا تجزیہ شرینگاررس کے ان چاروں منازل کی روشنی میں جس طرح کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنسکرت جمالیات پر ان کو دسترس حاصل ہے۔
فراق کی شاعری میں بھی شکیل الرحمٰن نے جنسی محبت کے شدید جذبہ کو دریافت کیا ہے۔انہوں نے فراق کی شاعری میں دو آرچ ٹائپس(Archetypes) تحرک یعنی ’رات ‘اور ’عورت‘کی موجودگی پراظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دونوں فراق کی سائیکی میں اترے ہوئے ہیں اور ان کی جمالیات مختلف رنگوں اور جہتوں کے ساتھ نمایاں ہوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے فراق کاوجود رقص کرتا ہوا معلوم ہوتاہے۔ شکیل الرحمٰن نے فراق کی جمالیات میں عورت،اس کے جسم اور اس کے پورے وجود کو جمالِ کائنات کا نقش قراردیا ہے اور کہا ہے کہ اس عمل میں ’سیکس‘کی لہروں کی شدّت موجود رہتی ہے۔شکیل الرحمٰن کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہرِسنسکرت جمالیات بھرت کے ایجاد کردہ انتہائی پُراثر’’رتی بھَو‘‘ کے ارتعاشات فراق کی شاعری میں بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے فراق کی شاعری میں انتہائی پرکشش ’جمالیاتی‘ فینومینن خلق ہوگیا ہے ۔شکیل الرحمٰن نے ہندوستانی جمالیات اوربدھ مفکرومعلم جمالیات اشوگھوش،جس نے فنی تخلیق سے جمالیاتی انبساط پانے کی جانب اشارے کیے تھے کے حوالے سے ’مہا سکھا‘کی اصطلاح سے جمالیاتی انبساط کو سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ فراق کی شاعری سے وہی انبساط حاصل ہوتا ہے جو’’یوگ اور سیکس کی ہم آہنگی کے تجربے سے ہوتا ہے۔
شکیل الرحمٰن نے’’ آہنگ‘‘ کو موسیقی کی اصل روح قرار دیاہے اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی شے نہیں ہے جس میں ہم آہنگی موجود نہ ہو۔انہوں نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا کوآواز، آہنگ اور روشنی کا ظہور سمجھا گیا ہے۔سورج اس فکرونظر کی بنیادی مرکزی علامت ہے۔انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ سورج(سوریہ)کی روشنی کے ساتوںرنگ موسیقی میں سات ’سروں‘ سے قریب ہیں۔’سوریہ‘روشنی اور آواز دونوں کی علامت ہے۔اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ روشنی اور آواز کی ہم آہنگی سوریہ ہے۔
دنیا کے تمام مقدس یا آسمانی کتابوں میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایک خاص نظام کے تحت اس کائنات کی تخلیق کی اور تخلیق کردہ موجودات میں ہم آہنگی پیدا کی۔ مثلاًچاند، سورج اور زمین اپنے اپنے مدار میں ایک دوسرے کی گردش ایک نظام کے تحت کرتے ہیں جس کی وجہ سے صبح ہوتی ہے،دن ہوتا ہے ،شام ہوتی ہے پھر رات ہوتی ہے اور یوںہی وقت گزرتا رہتا ہے یعنی ان تینوںسیاروں میں بھی ہم آہنگی پائی جاتی ہے اوران میں ہونے والے تغیرات کے اثرات بلاواسطہ یا با لواسطہ طور پر بے شمار چیزوںپر پڑتے ہیں۔آسمان،زمین اور سمندر میں پائی جانے والی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جن کا رشتہ دوسری چیزوں سے نہ ہواور ان میں ہونے والے تغیرات کے اثرات ایک دوسرے پر نہ پڑتے ہوں اور ان تمام چیزوں میں ہم آہنگی نہ پائی جاتی ہو ۔لہٰذا کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے انسانی رشتے بھی قائم نہ ہو سکیں۔اس کی وضاحت علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں اس طرح کی ہے
فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز
آہنگ میں یکتا صفتِ سورۂ رحمن
شکیل الرحمن نے شاعری میں ’’آہنگ‘‘ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے لکھا ہے کہ شاعری میںاکثر دو مصرعے جب ایک دوسرے میں جذب ہوجاتے ہیں تو بہاؤ کے ساتھ ایک جذبہ خلق ہوجاتا ہے، آہنگ کی ایک جمالیاتی تصویرابھرآتی ہے۔شکیل الرحمٰن نے آہنگ کے کرشمے کوفراق کی شاعری میں دریافت کیا ہے۔ان کا خیال ہے کہ فراق نے ادبی روایات کے جلال وجمال کے آہنگ کی مکمل طور پر نمائندگی کی ہے۔ان کی شاعری میں لفظوں کی تکرار نے شاعر کی حسی اور لمسی کیفیتوں کو تخلیقی سطح پر حد درجہ محسوس بنا دیاہے۔
شکیل الرحمن نے فراق کی شاعری میں ’شب‘اور’شام‘ کے استعمال سے عجیب وغریب کیفیت پیدا ہونے پرگفتگو کرتے ہوئے رات کے فلسفہ پرجس طرح روشنی ڈالی ہے اور اس کی خوبیوں اور پراسرارکیفیتوں کی وضاحت کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات کی تاریکی کو دن کی روشنی پر ترجیح دیتے ہیں۔انہوں نے بعض مذہبی خیالات کے حوالے سے لکھا ہے کہ اﷲتعالیٰ نے دن کی روشنی سے رات کو جنم دیا ہے لیکن بے شمارمثالوں اور دلیلوں سے رات کی تاریکی کودن کی روشنی سے افضل قرار دیا ہے۔اس سلسلے میں انہوں نے ممتازمصوّرVincent Van Gogh کے اس خیال سے اتفاق کیا کہ رات دن سے زیادہ زندہ اور مختلف گہرے رنگوں کو لیے ہوتی ہے۔اس کی وضاحت انہوں نے اس طرح کی ہے
’’اس کی تصویروں میں اکثرمحسوس ہوتا ہے جیسے رات ابدی حسن کے اسرار لیے سرگوشی کررہی ہے۔شب کی عطا کی ہوئی تاریکی جتنی گہری اور پراسرار ہوتی ہے اُتنی دن کی روشنی نہیںہوتی ۔دن کی روشنی میں وہ تہداری کہاں جو رات کی تاریکی میں ہے۔شب کے اسرار اور اس کی تاریکی سے جو جمالیاتی لذت اور انبساط حاصل ہوتا ہے وہ روح میں جان پرور کیفیت پیدا کردیتاہے۔‘‘
اسی لیے شکیل الرحمٰن کا خیال ہے کہ فراق کی شاعری میں’’ شب،شام اوراحساس وادراک کی ہم آہنگی اور وحدت سے ایک عمدہ جمالیاتی منظرنامہ سامنے آگیا ہے ،جس سے حسّی سطح پر جذباتی رومانی قدروں کا مطالعہ جمالیاتی انبساط بخشنے لگتاہے‘‘۔انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ فراق نے شب اور آہنگ ِشب سے جوباطنی رشتہ قائم کیا ہے اس سے ان کی شاعری میں میلوڈی پیدا ہوگئی ہے۔شکیل الرحمٰن نے فراق کی شاعری کوکئی رسوں کا مجموعہ قرار دیا ہے۔
شکیل الرحمن نے ادب اور آرٹ کی تخلیق میں اساطیر کی اہمیت پر زور دیا ہے کیوں کہ شاہد ہی کوئی اعلیٰ درجہ کا ادب یا فن لطیف ہوجس کی تخلیق میں شعوری یا غیر شعوری طور پراساطیر کے اثرات موجود نہ ہوں۔شکیل الرحمٰن کا خیال ہے کہ اساطیری روایت اور کردار تخلیق کار یا فنکار کے لاشعورکی گہرائیوںمیں موجود رہتے ہیں۔اجتماعی یا نسلی شعور سے اساطیر کی لہریں نا محسوس طور پر آتی رہتی ہیں اور شعور کو متاثر کرتی رہتی ہیں۔اسی لیے کوئی بھی بڑا تخلیقی فنکار اساطیر سے گریزنہیں کرسکتا۔اسی لئے انہوں نے اساطیر کو ایک خاموش متحرک روایت سے تعبیر کیا ہے جس کا سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے اور تخلیقی آرٹ کا باطنی رشتہ کسی نہ کسی سطح پر اساطیر اوراس کی روایت سے قائم رہتا ہے۔’’آرچ ٹائپ‘‘ کی توضیح وتشریح پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ تخلیقی فنکاروں کی حسی اور نفسی کیفیتوں کی شدّت سے آرچ ٹائپ میں تحرک پیدا ہوتا ہے اور بنیادی اور قدیم علامتیں اپنی تہداری اور معنی خیزجہتوں کے ساتھ نمایاںہونے لگتی ہیں۔شکیل الرحمن نے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ لوک کہانیوں کی جڑیں اساطیر کی گہرائیوں میں پائی جاتی ہیں ۔انہوں نے ایسے لوگوں کوبے جڑ کا پودا قرار دیا ہے جو متِھ اورلوک کہانیوں کے بغیر رہتے ہیں ۔ ان کا خیال ہے کہ لوک کہانیاں اعلیٰ درجہ کی جدید تخلیق کا سرچشمہ ہیں۔
لوک کہانیوںمیں فینتاسی کی خاص اہمیت ہے۔بلکہ اس کے بغیر لوک کہانیوں کا تصورہی نہیں کیا جا سکتا۔لوک کہانیوں کے اثرسے فینتاسی اردو کی کلاسیکی شاعری میں بھی پائی جاتی ہے لیکن اردوکے پہلے ناقدمولانا حالی نے ادب میں فینتاسی(Fantasy) کی تخلیق یا مافوق الفطرت عناصر کے استعمال پرسخت تنقید کی تھی کیوں کہ یہ خواب وخیال کی دنیا خلق کرتی ہے جو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔اس کے بعد تمام ناقدین نے مولانا حالی سے اتفاق کرتے ہوئے فینتاسی کو ادب میں ممنوع قرار دے دیا لیکن شکیل الرحمٰن ناقدین کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔فینتاسی کے متعلق ان کا خیال ہے کہ یہ تخلیقی فکرونظر کی ایک صورت ہے اور انسان کی نفسیات سے اس کا گہرا رشتہ ہے۔شکیل الرحمن نے کارل مارکس کے حوالے سے اس کی اہمیت پرروشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ انسان کی ترقی اور اس کی فکری ارتقا میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔اس کی اہمیت صرف ادبیات ہی میں نہیں بلکہ مصوری،موسیقی،فیزکس اور علم ریاضی میں بھی ہے۔ شکیل الرحمٰن نے اسے ذہن کا وہ نفسیاتی عمل قرار دیا ہے جس سے نئی دوربینی پیدا ہوتی ہے اور وژن نئی صورتوںکوپانے لگتاہے۔کلیات غالب اور اردو کی کلاسیکی مثنویوں میں شکیل الرحمٰن نے فینتاسی کے کمالات پر سیرحاصل بحث کی ہے۔ان کے مطابق اردو ادب میں غالب فینتاسی کے سب سے بڑے تخلیقی فنکار ہیں جن کی سائیکی نے ’امیجری‘کوصرف خلق ہی نہیں کیا بلکہ اسے توانائی بھی بخشی۔غالب کے علاوہ فینتاسی کی عمدہ مثالیں اردوکی کلاسیکی مثنویوں میں ملتی ہیں۔دراصل ان مثنویوں کا تعلق عوامی قصّوں اور دیومالا سے بھی رہا ہے اسی لئے مثنوی نگاروں نے ان قصّوں میں تصادم اورکشمکش کی پیشکش کے لیے فینتاسی پیدا کرنے کی کوشش کی۔شکیل الرحمٰن نے کدم راوپدم راو،قطب مشتری،سیف الملوک اور بدیع الجمال،چندربدن اورمہیار،پھول بن،گلشن عشق اورطوطی نامہ وغیرہ مثنویوں میں فینتاسی کے جوجوہر ملتے ہیں ان پراظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان مثنویوں میں جو فینتاسی پیدا کی گئی ہے، وہ اس لیے بھی پُرکشش ہیں کہ ہمارے لا شعورمیں ان کا حسن اور ان کے تحیر کا حسن موجود ہے۔فینتاسی کے کرداروں کی نفسیات یا ان کے ہیجانات ہم سے علاحدہ نہیں ہیںکیوں کہ مسرتوں اور اداسیوں کی نہ جانے کتنی داستانیں ہم اپنے لاشعورمیں لیے پھرتے ہیں۔غرض شکیل الرحمن کی تنقید ہندوستانی تہذیب کی جڑوں سے وابستہ ہے۔
سنسکرت جمالیات میں ’’اَدبھُت رَس‘‘یعنی تحیر کی جمالیات کی اہمیت پربہت زور دیا گیا ہے ۔شکیل الرحمٰن نے ابھینو گپت،بھرت منی،ممٹ اور اچاریہ نارائن کے حوالوں کی روشنی میں اَدبھُت رَس یا چمتکار رس یا ’لوکوٹ تارا(Lokottara)پر جس طرح بحث کی ہے اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے اسے پڑھ کر قاری خود ’اَدبھُت رَس‘میں ڈوب جاتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنسکرت جمالیات پر ان کی نظرکتنی گہری ہے۔وہ لکھتے ہیں
’’ تحیر رسوں کا نقطۂ عروج ہے، تحیر کی جمالیات کے بغیر کسی بھی اعلیٰ فن کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ تخلیقی آرٹ میں تحیر کی جمالیات قاری کے ذہن میں کشادگی پیدا کر کے اسے ایک افضل سطح پر لے جاتی ہے۔ یہ وہ سطح ہے جو زندگی کے جلال و جمال کو صرف حد درجہ مقوی ہی نہیں بناتی بلکہ زندگی کے حسن کو دیکھنے کے لیے ایک وژن بھی عطا کردیتی ہے۔‘‘
انہوںنے غالب کی ’’مثنوی چراغِ دیر‘‘کا مطالعہ اَدبھُت رس یعنی تحیر کی جمالیات کی روشنی میں کرکے غالب کی تنقید کا ایک نیا پہلو ایجاد کیا ہے۔ غالب کی مثنوی میں جو تحیرکی کیفیت پائی جاتی ہے اس پر گفتگو کرتے ہوئے شکیل الرحمٰن نے کہا ہے کہ کالی داس نے اپنی شاعری میں تحیر پیدا کرنے کے لیے پرانی ایپک سے فوق الفطری کیفیتوں کا سہارا لیا تھا لیکن غالب اپنی شاعری میں ادبھُت تجربوں کے لیے کسی رزمیہ یا ایپک کے پاس نہیں گئے بلکہ اپنی سائیکی کی مدد سے شاعری میں اَدبھُت رس یا تحیر پیداکیا جس نے ان کی شاعری کوعظیم سے عظیم تر بنا دیا۔شکیل الرحمٰن نے غالب کی مثنوی چراغِ دیر کے کینوس میں تین رنگوں کو دریافت کیا ہے جس میں پہلاسرخ رنگ جو جبلت کا رنگ ہے، دوسراآسمانی جو آسمان کا رنگ ہونے ساتھ ساتھ روح اور باطن کا رنگ بھی ہے اور تیسرااس سرخ اور نیلے کے امتزاج سے بنا ہے یعنی بنفشی(Violet)جسے صوفیانہ فکر کا رنگ کہا جاتا ہے۔ان رنگوں کی موجودگی نے مثنوی میں جو جمالیاتی وحدت پیدا کی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شکیل الرحمٰن نے کہا ہے کہ اس سے حیرت انگیز مسرت حاصل ہوتی ہے۔ان رنگوں کی مدد سے بنارس کے حسن کاتحیرجو جمالِ زندگی کی علامت ہے، کے پس منظر میں جس طرح جلال و جمال کے تحیر کو ابھارا گیا ہے ، وہ ایک بڑے تخلیقی فنکار ہی کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔
شکیل الرحمن نے غالب کاتہذیبی مطالعہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ غالب ایک تہذیب کی طرح پھیلے ہوئے تھے اوروہ ہندمغل جمالیات کی زندہ مثال تھے۔ان کے شعوراور لاشعور میں داستان ایک مستقل روایت کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے ان کی شاعری اور نثری تخلیقات میںاساطیری اور داستانی رجحان حددرجہ متحرک ہے۔غالب دراصل ایک ایسا تخلیق کار تھا جنہوں نے برصغیر کے بے شمار قصوں،کہانیوں اورداستانوںکی عظیم روایتوں سے تخلیقی نوعیت کا رشتہ قائم کررکھاتھا جن کا انعکاس ان کی تخلیقات میں موجود ہے۔شکیل الرحمٰن نے غالب کی نثری اور شعری تخلیقات سے متعدد مثالیں پیش کی ہیں جن میں دیومالا،قصص،مذہب اورامیجری کی وہ کائنات ہے جو داستانیت کے تحیر اور اس کی فینتاسی(Fantasy) سے تخلیقی رشتہ رکھتی ہے۔ شکیل الرحمن کے مطابق غالب کی تخلیقات میں جو فکر کی توانائی اور تخیل کی بلند پروازی پائی جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غالب نے ہندمغل تہذیب کی بے پناہ گہرائیوں میں اپنی جڑیں پھیلا رکھی تھیں۔
روشنی،رنگ اور رفتارکے درمیان گہرا رشتہ ہے۔روشنی میں کئی رنگ پنہاںہیں لیکن اس کی رفتارشدید تیزہونے کی وجہ سے اس کے رنگ نظر نہیںآتے ہیں البتہ انہیں Prism یا قوسِ قزح میں دیکھا جا سکتا ہے۔ شکیل الرحمٰن نے اقبال کی شاعری میں استعارہ کے طور پرروشنی کے استعمال کی فلسفیانہ توضیح پیش کی ہے۔دراصل اشراقی فلسفہ کے مطابق نور اعلیٰ تمام حرکات کا مبدا ہے اور حرکت کا سبب منور کرنے کی خواہش ہے اوریہی وہ خواہش ہے جو نور کو مضطرب کردیتی ہے تاکہ یہ اپنی شعاعوں کوتمام چیزوں پر منعکس کرکے ان کی زندگی میں ایک روح پھونک دے۔اس سے جو تجلیات نمو کرتی ہیں ان کی تعداد لا محدود ہوتی ہے اور ایسی تجلیات جن کی روشنی شدید ہوتی ہے وہ دوسری تجلیات کاسرچشمہ بن جاتی ہیں۔گویا یہ کائنات ایک سایہ ہے ان بے پناہ تجلیوں کی شعاعوں کاجو نوراعلیٰ سے آتی ہیں۔کائنات کی اشیامیں ان تجلیوں کے سبب جن کی جانب یہ مستقل حرکت میں رہتی ہیں ایک عشق کا جذبہ نمو پاتا رہتا ہے تاکہ وہ حقیقی نور کے سرچشمہ سے مستفیض ہوتی رہیں۔یعنی یہ کارخانۂ عالم محبت وعشق کا ابدی ڈرامہ ہے۔اسی لئے شکیل الرحمٰن نے اشارہ کیا ہے کہ اقبال کی شاعری میں عشق ایک ہمہ گیر تخلیقی جذبہ ہے اور عشق کی گرمی سے ہی معرکۂ کائنات ہے۔اقبال کے اس شعر
عشق کی جست نے کردیا قصّہ تمام
اس زمین وآسماں کو بیکراں سمجھا تھا میں
پر تبصرہ کرتے ہوئے شکیل الرحمٰن نے ’روشنی‘ کی جمالیات کی توضیح اس طرح کی ہے کہ عشق سے روشنی کا شعور حاصل ہوا اور تنویر نگاہ سے کائناتی جلوؤں کی پہچان ہوئی اور لامکاں کی روشنیوں کا ادراک حاصل ہوا۔انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ نگاہ،نگاہِ شوق اور نظر بطور استعارہ استعمال ہونے کے پیچھے ’’روشنی‘‘کا ’آرچ ٹائپ ‘حددرجہ متحرک ہے۔ شکیل الرحمن نے فکروفلسفہ کی جس بلندی پر پہنچ کر اقبال کی شاعری میں روشنی، رنگ اور رفتار بطور استعارہ اور علامت استعمال کئے جانے کا جو جواز پیش کیا ہے، وہاں تک پہنچنے میں بڑے سے بڑے ماہر اقبالیات کی پوری زندگی ختم ہوجائے گی۔انہوں نے مطالعہ اقبال کا نظریہ ہی بدل دیا ہے۔
امیر خسرو حسن ازلی،حسن انسانی اور حسن حیات وکائنات کے ایک بڑے شاعرہیں،حسن کے مظہرکے عاشق ہیںاور ’’ہیومنزم‘‘(Humanism ) ان کے کلام کا اصل جوہر ہے کیوں کہ انسان ہی وہ مخلوق ہے جو حسن مطلق اور حسن کائنات کو دیکھنے اور محسوس کرنے کا وژن رکھتا ہے۔شکیل الرحمن نے انسان کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہہ کر کہ’’ انسان روح کی مانند کائنات میں سماجاتا ہے اور اس میں تحرک پیدا کردیتا ہے اور یہ بھی سچائی ہے کہ یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ انسان کا وجود اس میں سماہی نہیں سکتا۔‘‘ابن عربی کے اس قول کی طرف اشارہ کردیا ہے کہ انسان خدا کا آئینہ ہے اور خدا انسان کا آئینہ ہے۔تبھی تو انسان کا وجود اتنی چھوٹی سی دنیا میں سما نہیں سکتا ہے۔انسان روح کی مانند دنیا میں سما کر تحرک پیدا کرسکتا ہے تو پھر وہ انسان ہی ہے جو کائنات کے ہر شے کے جمال اور زندگی کے تمام رنگوں کا عاشق ہے۔امیرخسرو نے اپنی شاعری میں رنگ اور روشنی کے علاوہ سیاہی یا ظلمت کے حسن کو بھی پہچاننے کی بات کہی ہے۔دراصل فلسفیوں کا خیال ہے کہ ظلمت کوئی ایسی متمائزشے نہیں جو کسی قائم بالذات ماخذسے ظہور کرتی ہو بلکہ نور کے اثبات میں ہی اس کی نفی پوشیدہ ہے، یعنی یہ خود کو قائم رکھنے کے لیے ظلمت کو منور کردیتا ہے۔ اسی لیے شکیل الرحمٰن کا خیال ہے کہ سیاہی کے حسن کے جلوے کو بھی جس نے پہچان لیا دراصل وہی صاحب فکرونظر ہے، جمال وجلال کا رسیا ہے، خالق کی تخلیقات کے حسن کا حصہ اور جوہر ہے۔شکیل الرحمٰن نے امیر خسروکی جمالیات کے ضمن میں جس طرح انسان کی عظمت، مظاہر خدا اور مناظر کائنات پر روشنی ڈالی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تصوف کے رموز سے بخوبی واقف ہیں۔
شکیل الرحمن اپنے ہر مضمون میں ایک نیا زاویہ پیش کرتے ہیں۔مثلاًاسلوبیات کے موضوع پر اب تک جتنی کتابیں اور مضامین لکھے گئے ہیں ان میں تمام ماہرینِ اسلوبیات نے صرف خارجی پہلوؤں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے لیکن شکیل الرحمٰن نے ترجمان القرآن کے اسلوب کا جائزہ پیش کرتے ہوئے اس کے باطنی پہلوکی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم میں روح کی جو اہمیت ہے وہی اہمیت اسلوب میں باطنی پہلو کی بھی ہے جس کی بہترین مثالیں مولانا ابوالکلام آزاد کی تخلیقات میں موجودہیں۔شکیل الرحمٰن کے مطابق ترجمان القرآن کااسلوب جوابلاغ کااپناحسن رکھتاہے، تزکیہ نفس بھی کرتاہے اورایک معروضیObjective زاویہ نگاہ بھی عطا کرتا ہے۔شکیل الرحمٰن کا خیال ہے کہ اب تک قرآن کی متعدد تفسیریں لکھی جاچکی ہیں لیکن ان میں بیشتر تفسیروں کا اسلوب عربی آمیزہے ۔اردو کلچر میں پوری طرح ڈھل نہیں پائی ہیں جس سے بعض مفاہیم کی تشریح پیچیدہ معلوم ہوتی ہے لیکن مولانا نے قرآن کے آہنگ کواپنی شخصیت میں پوری طرح جذب کرکے اس کے دقیق سے دقیق مسائل کو بھی اس کی اصل روح کو برقراررکھتے ہوئے اردو تہذیب کے سانچے میں ایسے ڈھال دیا ہے کہ اسے پڑھ کر بعض ایسی سچائیاں اور حقیقتیں قاری پر منکشف ہوجاتی ہیں کہ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ شکیل الرحمن نے جہاں مولانا کی اردو زبان وادب پر بے پناہ قدرت کی بات کہی ہے وہیں اردو کلچراورزبان کی توانائی اور برقی کیفیتوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کس طرح قرآن کا جلال وجمال اردو کے سانچے میں ڈھل گیا۔وہ لکھتے ہیں کہ’’ قرآن مجید کی پاکیزہ خوشبوؤں سے قاری کے احساس وشعور اور اس کے پورے وجود کو معطر کرنے کا جو اسلوب مولانانے خلق کیا ہے وہ ان کی پچھلی تحریروں کے اسالیب سے مختلف تو ہے ہی ،تسویہ ، مطابقت اور ہم آہنگیHarmony کا بھی منفرد اور خوبصورت نمونہ ہے۔ ‘‘
مولانا ابوالکلام آزادنے ترجمان القرآن کے علاوہ غبارِخاطر میں بھی نثری اسلوب کا جادو جگایا ہے۔احمد نگر کے قلعہ میںنظربند ہونے کے دوران لکھے گئے تمام مضامین یقینا ان کے دل کے غبار ہی ہیں لیکن مولانا نے اس غبار کونثر کے سانچے میں ڈھالنے کے لئے قلعہ کے بند کمرے میں اپنی ایک الگ دنیا بنائی جس میں قدرت کے تمام رنگین نظارے،قطاردرقطار خوشبو بکھیرتے ہوئے پھول اورنغمے گاتے ہوئے پرندے موجود تھے۔اس لیے ان کے نثری اسلوب میں ایسی کیفیت پیدا ہوگئی ہے کہ ہر شخص اس کی طرف کھنچتاچلاجاتا ہے۔غبارخاطر کی نغمگی اور خوشبونے شکیل الرحمٰن کو بھی اپنی طرف کھینچا اور انہوں نے مولانا کے مضامین میںان کی رومانیت کودریافت کیا ۔مولانا کی رومانیت کو دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ شکیل الرحمٰن نے رومانیت کی جمالیات کی طرف جو اشارے کئے ہیں وہ قابلِ تعریف ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ ’’رومانیت انجمن سے نکل کر تنہائی کی ایسی فضا چاہتی ہے،جہاں احساسات پر کسی قسم کی گرفت نہ ہو‘‘۔ شکیل الرحمٰن کا خیال ہے کہ رومانی فنکار کو اپنے باطن کی سرمستیاں اس قدر عزیز ہیں اور وہ انہیں اس قدرعزیز جانتا ہے کہ انہیں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا ہے۔رومانیت باطن کی آگہی ہے۔باطن کی روشنیوں کے تئیں بیداری ہے‘‘۔ شکیل الرحمٰن نے مولانا کی رومانیت پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فطرت کا حسن اور انسان کی تخلیقات کا حسن،دونوں فنکار کی رومانیت کو بیدار اور متحرک کئے رہتے ہیں۔مولانا کی رومانیت میں علم کا دباؤ نہیں ہے اورحسن سے ایک معصوم سا رشتہ قائم ہے۔علم سے جو آگہی حاصل ہوئی ہے اور حسن کو دیکھنے ومحسوس کرنے کا جو وژن ملا ہے اس کاجوہر بھی ان کی رومانیت میں موجود ہے۔
شکیل الرحمن کے تنقیدی تحرکات کی یہ چند تمثیلیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی تنقیدی لہروں کی دریافت کے لیے سمندر کی سطح چاہیے۔ ان کی تنقید میں ایک نئی روح ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان کا تنقیدی اسلوب دوسروں سے بالکل منفرد ہے ، وہ فکشن کی زبان میں تنقید لکھتے ہیں، اس لیے ان کی تنقید بنیادی طور پر تخلیقی تنقید ہے ، ان کی بعض عبارتیں تو ایسی ہیں جنہیں پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ نثر نہیںشعری واحدے ہیں۔