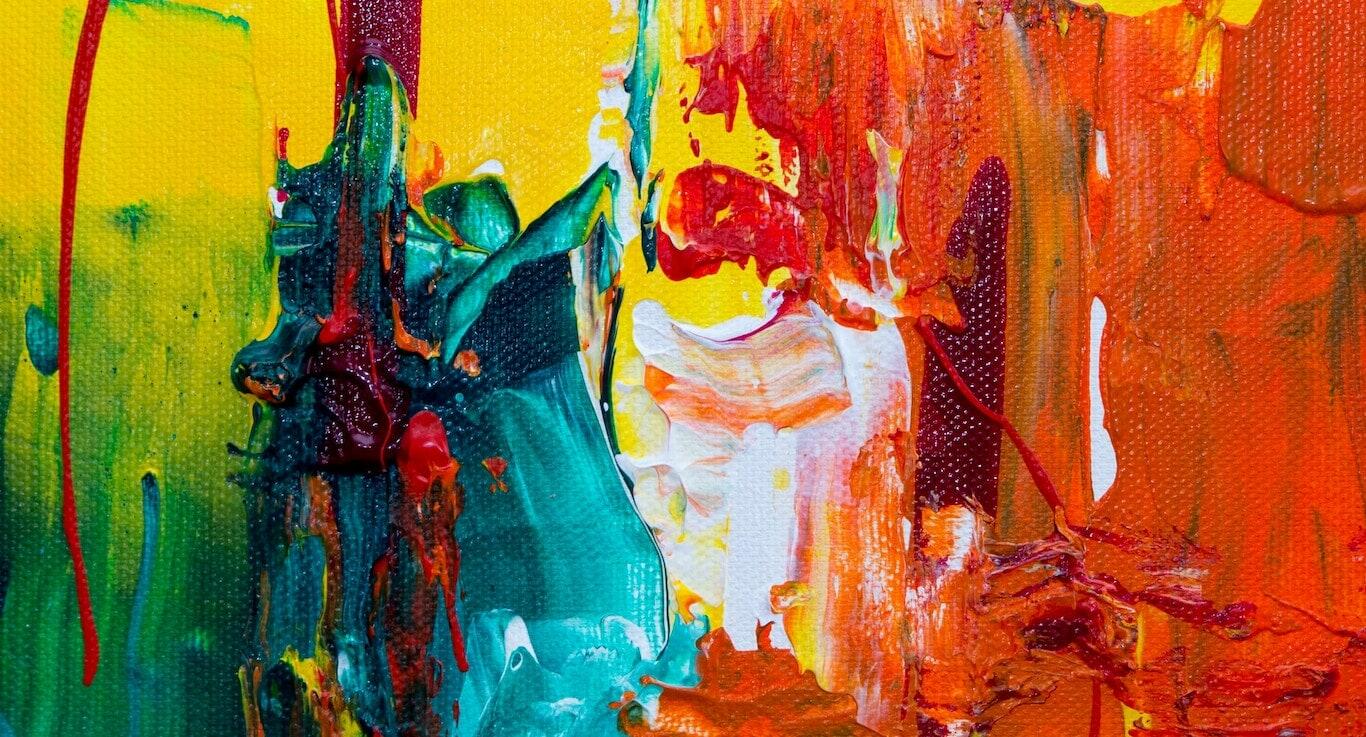ہم عصر تنقیدی رویّے
فلسفہ اورتھیوری کبھی آفاقی نہیں ہوتے ہیںاس کی اہمیت علاقائی یاملکی سطح پرہوتی ہے۔فلسفہ اگرآفاقی ہوتا توکمیونزم چند ممالک کے بجائے پوری دنیامیں پھیل جاتی ۔اسی طرح گاندھی جی کا فلسفہ ستیہ اوراہنسا صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ عالمی سطح بھی پر قبول کیا جاتا۔ فلسفہ اس وقت جنم لیتاہے جب سماجی ،سیاسی اورمعاشی بحران پیدا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت سے نجات دلانے کے لیے مفکرین کوئی ایسا راستہ یا طریقہ ڈھونڈتے ہیں جو سب کے لیے قابلِ قبول ہو تواسے فلسفہ کہتے ہیں۔ فلسفہ سب کے لیے قابلِ قبول اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہماری تہذیبی وراثت اورتہذیب کی اصل روح سے مطابقت رکھتا ہو۔نظریہ ،فلسفہ کے زیرِ اثرغورفکرکے تجدیدی اورمنطقی ضابطہ اورعمومی سوچ کے ذریعہ پیداہوتاہے اور اکثرعام اصولوں پرمبنی ہوتا ہے ۔نظراور فلسفہ وہیںرونما ہوتے ہیں جہاںان کی ضرورت ہوتی ہے۔
’’نظریہ‘‘ کو’’ادبی نظریہ‘‘ یا’’ تنقیدی نظریہ‘‘یا ’’فلسفۂ ادب‘‘ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ادبی نظریہ دراصل ’’نظریۂ علم‘‘ یا’’ علمیات‘‘ کی ایک شاخ ہے جس کے متعلق کانٹ کہتا ہے کہ ’’یہ انتقاد علم کا علم ہے‘‘اورنٹشے کہتا ہے کہ ’’علم وآگہی کا علم ہے‘‘۔ ’’ادبی نظریہ‘‘ کی تعریف یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ یہ ذہن میں قائم تصور اور طریقۂ کار کے ایک امتزاج کا نام ہے جس کا استعمال تخلیقِ ادب کے ساتھ ساتھ تفہیم ِادب میں بھی کیا جاتا رہا ہے ۔’ادبی نظریہ ‘ بنیادی اصولوں کی وضاحت کرتا ہے اس لیے اسے Tool سے بھی تعبیر کیاجاتاہے، جس کی مددسے ہم ادب کوسمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔تمام ادبی توضیح یاتشریح نظریہ کی بنیادپرکی جاتی ہے۔یہ’ ادبی نظریہ‘ ہی ہے جومصنف اورمتن کے درمیان رشتہ کووضع کرتاہے۔نظریہ مصنف کی سوانح عمری اورمتون میں موجودان موضوعات کے نقطۂ نظرسے ادب میں نسل،طبقہ اورجنس کے مطالعہ کی اہمیت کااحساس دلاتاہے۔ادبی نظریہ متن کی تشریح وتوضیح میں تاریخی تناظر ولسانی کردار اور متن میں موجود لاشعوری عناصرکوسمجھنے کے لیے مختلف نقطۂ نظرپیش کرتاہے۔حالیہ برسوں میں ادبی نظریات نے یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ متن مصنف سے کہیں زیادہ تہہ دار بامعنی ، پیچیدہ اور تکثیری مزاج کا حامل ہوتاہے جس سے تمدن ، تہذیب اورثقافت کے کئی پہلوؤں کی تعمیر و تشکیل ہو سکتی ہے۔
وقت اور حالات جب بدلتے ہیں تو سماجی، سیاسی، تہذیبی اور اقداری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان تبدیلیوں کے زیراثرادبی نظریے بھی بدل جاتے ہیں ۔نظریے بنتے اوربگڑتے رہتے ہیں لیکن مکمل طور پرختم نہیں ہوتے البتہ ان کے اثرات ضرورکم ہوجاتے ہیں ۔ تنقیدی رویّے ادبی نظریوں سے پیدا ہوتے ہیں۔اس لیے نظریے کے ساتھ ساتھ تنقیدی رویّے بھی بدل جاتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ تنقیدی رویّے ، نظریے کے عین مطابق ہوں۔رویّے، نظریے کے تمام دائروں کوتوڑ بھی دیتے ہیں۔ تنقیدی نظریوں اور رویّوں میں جب تبدیلی آتی ہے توروشن خیال ناقدین نئی تبدیلیوں کاخیرمقدم کھلے دل سے کرتے ہیں اور اسے وقت کی ضرورت سمجھ کر تنقیدی رویّوں میں بھی رفتہ رفتہ تبدیلی لاتے ہیں لیکن بعض قدامت پسند،، شدت پسنداور کسی خاص ادبی گروہ بندی کے شکارادیب و ناقدین خود کو نئے نظریے اور رویّے کے سانچے میں نہیں ڈھال پاتے ہیں جس کی وجہ سے نئی نسل کے ساتھ ان کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوپاتی ہے۔تنقیدی ر ویّے سے مراد یہ ہے کہ ادب شناسی کے تفاعل کے دوران نقاد، مصنف کو ترجیح دے رہا ہے یا متن کو، پھرقاری کو یا تناظر(تاریخی ،سماجی،سیاسی اورتہذیبی)کویا پھرزبان وبیان کو۔پروفیسر گوپی چند نارنگ نے ایم ایچ ابرمز(M.H.Abrams) کے ایک ایسے نقشے کی مددسے سمجھایاہے جس کے مرکز میں متن ہے اور مدار میں برابر فاصلے پرکائنات ،مصنف اور سامعین(قارئین) ہیںجومعنی خیزی میں شریک ہیں،کی تنقیدی عمل کے دوران مصنف پرزور دینے سے اظہاری (Expressive) رویہ، متن پر زور دینے سے معروضی(Objective)رویہ ، کائنات پر زور دینے سے نقالی (Mimetic)کارویہ اور قاری پر زور دینے سے عملی (Pragmatic)رویہ وجودمیں آتاہے۔ بعض ناقدین متن کا مطالعہ تاریخ کی روشنی میں کرتے ہیں تو بعض متن کو تہذیب کے آئینہ میں دیکھتے ہیں۔کچھ ناقدین کسی خاص ازم یا تحریک یا کسی خاص رجحان یا رویّے کے اصول کے تحت متن کی جانچ پرکھ کرتے ہیں تو کچھ اپنے ہی وضع کردہ جمالیاتی وژن سے متن کی اصل روح تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں توکچھ آرکی ٹائپ اصولوں کے مدنظر مصافحہ اور مکالمہ کرتے ہیں۔ان تمام ادبی نظریوں یا فلسفۂ ادب کی روشنی میں کسی متن کا مطالعہ کرتے وقت ہرنقاد کی پسندوناپسند اور قدریں بھی ہوتی ہیں جس کا عکس ان کی تنقیدی نگارشات میں موجود ہوتا ہے اس لیے ایک ہی نظریے یا اصول کو مانتے ہوئے بھی ہرناقد کا تنقیدی رویہ مختلف ہو سکتا ہے۔نظریہ ساز وں کا خیال ہے کہ متن کوجانچنے،پرکھنے اوراس پراظہار خیال کرنے کے لیے کسی نہ کسی نظریے کا تابع ہوناضروری ہے۔ لیکن تنقید کے لیے نظریہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔نظریہ، تنقید کا ایک اہم حربہ ضرور ہے لیکن تنقیدکے لیے زبان کا علم، روایت سے آگہی اورشعریات کی آگہی بھی ضروری ہے۔ بعض ناقدین تمام نظریوں سے واقف ہوتے ہیں لیکن کسی بھی نظریے یارویّے کے پابندنہیں ہوتے ہیں لیکن تنقیدی عمل سے گزرتے ہوئے اپناالگ نظریہ وضع کرلیتے ہیں ۔توپھراس نئے نظریے کا کیا نام دیا جانا چاہئے ؟یہ مسئلہ غور طلب اور بحث کا متقاضی ہے۔
ہم عصر تنقیدی روییّ کوسمجھنے کے لیے سابقہ ادبی نظریوں اوررویوںپرایک نظرڈالناضروری ہے۔جیسا کہ ہم سب جانتے ہیںاردوادب میں تنقید کا باقاعدہ آغاز مولاناحالی کے مقدمۂ شعروشاعری کے ساتھ ہوگیاتھا ۔حالی نے متن سے زیادہ مصنف کو ترجیح دی تھی پھربھی ان کی تصانیف اطلاقی تنقید یا عملی تنقید کی عمدہ مثالیں ہیں ۔حالی نے متن کی تنقیدمیں اخلاقی قدروں کو بھی ملحوظ خاطر رکھاتھا۔ حالی کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے ان کے ہم عصر ناقدین شبلی،آزاداورپھر عبدالحق،وحیدالدین سلیم اورنیاز فتح پوری وغیرہ نے بھی کم وبیش تنقید کے اسی رویّے کی پیروی کی۔تنقید کا یہ رویہ رومانی نظریے کے زیراثرپیداہواتھا جومغرب کی رومانیت سے ماخوذتھا۔واضح رہے کہ اردوادب پر مغربی رومانیت کااثر برسوں غالب رہا۔ان رومانی ،تاثراتی نقادوں کے بعدتنقیدمیں کچھ رویے ،رجحانات بھی سامنے آئے اورپھرکلیم الدین احمدکی آمد کے بعدتنقیدکامنظرنامہ بدلنے لگا کیوںکہ انہوں نے مغربی تنقید کے زیراثرادب کونئے نظریے سے پرکھنے کی کوشش کی۔چونکہ کلیم الدین احمدکا تعلق انگریزی ادب سے تھا اس لیے ان کا تنقیدی رویہ مغرب سے مستعارتھا۔کلیم الدین احمد کے ہم عصرناقدین میں محمد حسن عسکری اور آل احمد سروربھی تھے لیکن ان سب کا تنقیدی رویہ ایک دوسرے سے مختلف تھا کیوں کہ کلیم الدین احمد کی شعریات انگریزی ادب کی شعریات سے، محمد حسن عسکری کی شعریات فرانسیسی ادب کی شعریات سے جبکہ آل احمدسرور کی شعریات مشرقی شعریات سے ماخوذ تھی لیکن ان تینوں ناقدین نے تنقید میں مشرقی ومغربی تنقیدکے فرق کوختم کرنے کی کوشش کی۔اسی زمانے میں مارکسیت کے ساتھ ساتھ ترقی پسند نظریے اردوادب میں آہستہ روی کے ساتھ داخل ہونے لگے۔ترقی پسند ادب کاسرچشمہ اشتراکیت یا کمیونزم کا نقطۂ نظرہے جس کااولین مقصد سماج کے ڈھانچے کوبدلناتھا۔اس لیے ترقی پسندنظریہ ادب نے جواصول وضع کیا تھا اس کے مطابق ادب کوعوامی زندگی کاترجمان ہوناچاہئے اورادب کوآسان زبان میںعوام کے لیے لکھاجاناچاہئے اورسماج کے پس ماندہ طبقے کوادب میں زیرِ بحث لاناچاہیئے تاکہ سماج کی طبقاتی تقسیم کوختم کیاجاسکے اورغیرطبقاتی معاشرہ قائم کیاجاسکے۔اس نظریے کے تحت ترقی پسندتنقیدنے استعارہ سازی یا بالواسطہ اظہار سے اجتناب کیا۔ماضی کے مرصع ادب کوذہنی عیاشی کاعکاس قراردیا۔ترقی پسندنظریۂ ادب کے ز یر ادیبوں ناقدوں کی ایک جماعت سامنے آئی جس میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، اخترحسین رائے پوری، احتشام حسین اورسبط حسن وغیرہ تھے۔ ان نقادوںنے اس نظریے کا اطلاق اپنی تحریروں میں کیا لیکن اس نظریہ کی مضبوط اور منظم صورت سوائے احتشام حسین اور اخترحسین رائے پوری کے کسی کے یہاں نظر نہیں آتی ہے کیوں کہ ترقی پسندتنقید تھیوری سے دورتھی۔ اس دورکے ناقدین میں ممتاز حسین،مجنوں گورکھ پوری ،علی سردارجعفری اور عبادت بریلوی وغیرہ نے ادب کو ترقی پسندنظریے کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی جس سے حالی کے دور کے نظریے میں تبدیلی آنے لگی اور تنقیدی رویہ بدلنے لگا۔اس نظر یے کے تحت ناقدین نے مصنف اور تناظردونوں کو ترجیح دی اور ادب کو تاریخی وسماجی تناظرمیں پرکھنے کا رویہ حاوی ہونے لگا لیکن رفتہ رفتہ اس رویہ میں شدت آگئی اور مصنف، متن،تناظر،زبان اورقاری کے درمیان توازن قائم نہیں رہ سکا اورمتن کی جمالیاتی قدروقیمت سے نقادوں کی توجہہ ہٹ گئی ۔متن صرف پیغام بن کر رہ گیاجس سے تنقید مجروح ہونے لگی۔پھربھی ترقی پسند تنقیدکااثرادب پربرسوں رہا۔اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ تحریک آزادی کے ساتھ ساتھ پروان چڑھی اور اس نے عوامی بیداری، سماجی شعور،قومیت، رواداری،اتحاد پسندی،جوش وولولہ، تعمیروترقی میں اہم کردارنبھایا لیکن اس کے پاس ادب اورغیرادب میں فرق کرنے کے لیے کوئی واضح تھیوری نہیں تھی۔اس لیے آزادی کی تحریک ختم ہوجانے اورہندوستان وپاکستان کے وجودمیں آجانے کے بعد اس کااثرکم ہونے لگا اوراسی زمانے میں جدیدیت کا نظریہ بھی رونماہونے لگا ۔
جدیدیت جوترقی پسندی کی ضدمیں اُبھری تھی اورجوباغیانہ رویے کی دین تھی،وہ کسی بھی سیاسی نظریے کی رہنمائی کے خلاف تھی۔اس لیے اس نے ترقی پسندی کو رد کرنے میں اپنی پوری طاقت جھونک دی جس کی وجہ سے یہ زندگی اورثقافت کے تحرک سے کٹتی چلی گئی ۔لیکن جدیدیت نے آزادیٔ رائے اورآزادیٔ فکرکی پراصرارکیا۔جدیدیت نے ادب برائے ادب کی حمایت کی اورادب میں علامت نگاری، تہداری اورتشبیہ واستعارے کے استعمال اورنئے موضوعات،نئے تجربے اورنئے اسالیب پرزوردیا لیکن ادب کے سماجی منصب کی مخالفت کی۔جدیدیت نے فکری سطح پر فلسفہ ٔ وجودیت کی حمایت کی اورامریکی new criticism کوبنیادبنایاجس کی روسے متن پراصرارکیاگیا ۔نئی تنقید نے غلطی یہ کی کہ اس نے بھی اپنی نظریاتی بنیادوںکو واضح نہیں کیا۔اس کی دوسری غلطی یہ تھی کہ اس نے مصنف کے ساتھ ساتھ قاری کوبھی رد کردیا۔ ابتدائی دورمیں جدیدیت کی رہنمائی حسن عسکری اور بعدمیں آلِ احمد سرور نے کی۔جدیدیت کے نظریے کے زیرِ اثر متن کو سیاسی وسماجی تناظرمیں دیکھنے اور پرکھنے کا رویہ ختم ہوگیا۔متن کو ترجیح دی گئی لیکن قاری حاشیے پر چلاگیا۔جدیدیت کے حامی ناقدین وارث علوی،وزیر آغا، شمس الرحمٰن فاروقی ، مغنی تبسم ، حامدی کاشمیری ، فضیل جعفری اور وہاب اشرفی وغیرہ نے متن اور زبان کو اہمیت دی جس سے ادب میں گہرے مطالعہ اور تجزیے کا رویہ تیز ہوگیالیکن قاری کو بالکل نظراندازکردیا گیاجس کی وجہ سے ترقی پسندی کی طرح جدیدیت کی تنقید کا توازن بگڑ گیا اورکسی نئے نظریے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔
اسی ز مانے میں مابعدجدیدیت کابھی ظہورہواجس کی تشکیل میں سوسیر،لاکاں،رولاںبارتھ،پال دی مان،لیوتار،جولیاکرستیواوغیرہ نے اہم کردار نبھایاتھا۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح ترقی پسند نظریے کے ردعمل میں جدیدیت کا نظریہ وجودمیں آیا اسی طرح جدیدیت کے ردعمل میں مابعدجدیدنظریہ پیداہوالیکن اس نظریے کے ماہرین کاخیال ہے کہ مابعد جدیدنظریہ کسی بھی سابقہ نظریہ کے ردعمل میں نہیں آیا ہے بلکہ مابعدنظریے کی جڑیں مشرقی ادبیات میں پہلے سے موجودتھیں اوریہ کہ مابعدجدیدنظریہ کسی بھی نظریے کا مخالف نہیں ہے۔ بہرحال مابعدجدیدیت نے سابقہ تمام تنقیدی ترجیحات کوبڑی حدتک بدل دیا۔واضح رہے کہ مابعدجدیدیت کوئی نیانظام نہیں بناتی لیکن مابعدجدیدناقدین نے اس کی جوترجیحات وضع کی ہیں اس کی روشنی میں گوپی چندنارنگ نے لکھاہے
’’ساختیاتی فکرکی روسے متن خودمختاراورخود کفیل نہیں ہے۔یا یہ کہ معنی متن میں بالقوۃ موجود ہوتاہے،قاری اور قرأت کاعمل اس کوبالفعل موجود بناتاہے۔یا یہ کہ معنی وحدانی نہیں ہے، یہ تفریقی رشتوں سے پیداہوتاہے اورجتناظاہرہے اتناغیاب میں بھی ہے۔یا یہ کہ متن چوں کہ آئیڈیولوجی کی تشکیل ہے، ادب کی کسی بحث سے تاریخی،سیاسی،سماجی یاثقافتی معنی کااخراج نہ صرف غلط بلکہ گمراہ کن ہے۔ان بنیادی امورہی سے جوموقف مرتب ہوتا ہے وہ نئے ماڈل سے قریب تر ہے۔…اس موقف سے جوتنقیدی عمل مرتب ہوگا وہ روایتی یا جدید تنقید نہیں، پس ساختیاتی یامابعدجدید تنقید ہی کہلائے گا۔‘‘
متذکرہ ترجیحات کے مطابق مابعدجدید تنقیدمیں معنی کی تکثیریت سب سے اہم پہلوہے۔اس موضوع پرتمام مابعدجدیدنقادوں نے اظہار خیال کیا ہے اور سبھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ مصنف جب متن لکھ کرقاری کے حوالے کردیتاہے تواس متن سے دست بردارہوجاتاہے اورمتن قاری کی دسترس میں آجاتاہے۔اس کے بعد قاری کو یہ اختیار حاصل ہوجاتا ہے کہ متن کامطالعہ وہ جس طرح سے چاہے کرے اور معنی برآمدکرے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ تناظر کے بدل جانے کے ساتھ معنی بھی بدل جاتے ہیں۔متن کا مطالعہ تاریخی، سیاسی، سماجی،معاشی،تہذیبی ، سائنسی،ماحولیاتی کے علاوہ سیکڑوں تناظرمیں کیاجاسکتاہے اورمتن کے ہزاروں معنی برآمدکئے جاسکتے ہیں۔لہٰذا دریدا کا یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ Meaning is infinite ۔دریدا کا یہ کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ معنی جتنا حاضر میں ہے اتناہی غائب میں۔غالب نے بھی دعویٰ کیاہے کہ اس کے اشعارمیں جن الفاظ کااستعمال ہوا ہے انہیں گنجینۂ معنی کا طلسم سمجھا جھاجائے۔ وہ تویہ بھی کہتا ہے
دامِ شنیدن جس قدرچاہے بچھالے
مدعا عنقا ہے اپنے عالمِ تقریرکا
غالب کا فرمانا درست ہے۔غالب کی متعددشرحیں شائع ہوجانے کے باوجودبھی تفہیم غالب کا کام ہنوز جاری ہے اورآئندہ بھی جاری رہے گا۔
بعض صوفیہ کرام اور علما کا خیال ہے کہ کتب سماوی میں باطنی علوم کا ایک ابدی سرچشمہ جاری ہے لیکن انسانی ذہن حکمت الٰہی تک پہنچنے سے قاصرہے۔اسلامی عقیدے کے مطابق تمام علوم وفنون کا سرچشمہ ذات ربانی ہے۔حروف ،علم الاعداد اورہندسے وغیرہ اسی سرچشمے سے وجود میں آئے ہیں۔اسی لیے کہاجاتاہے کہ ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ میں علم ومعانی کی ایک دنیا آباد ہے ۔اس دنیامیں ہم اتناہی سیرکرسکتے ہیں جتنی کہ ہماری معلومات ہے۔ قرآن شریف میں حروف ِمقطعات میں آلٓم، ق م اور حٓمٰٓ وغیرہ، جس کے معنی آج تک کوئی نہیں بتا سکا۔ان کے معنی ومفہوم کی توضیح وتشریح ہنوز باقی ہے۔اس سے ظاہرہوتا ہے کہ صدیوں سے ادب میں تکثیریت کا تصور موجود ہے ۔دریدانے اگر اس تصوّر کوTheorise کردیا تو اس میںمضائقہ کیا ہے؟ بہرحال اس نظریے کے تحت قاری کومرکزیت حاصل ہوگئی اورادبی تنقیدمیں قاری کو اہمیت دی جانے لگی۔موجودہ تنقید میں یہ رویہ عام ہے۔
مابعدجدیدیت میں بین المتونیت کوبھی بہت اہمیت حاصل ہے کیوں کہ اس کی جڑیں ہندوستان کی ادبیات میں کا فی گہری ہیں۔سنسکرت زبان میں بین المتونیت کی بہترین مثال مہابھارت ہے۔مہابھارت میں پہلے صرف چارہزار شلوک تھے لیکن اب اس کے شلوک کی تعداد بڑھتے بڑھتے چار لاکھ ہوچکی ہے۔یعنی مہابھارت کے ماقبل متون میں لاتشکیلیت کا عمل صدیوں تک جاری رہا۔موجودہ دورمیں بھی مہابھارت کے متون میں لاتشکیلیت کا عمل جاری ہے اور اسے بنیاد بناکر ہندی اور اردومیں داستانیں، ناول اور افسانے لکھے جا رہے ہیں۔ موجودہ دورکے تخلیق کاروں میں انتظارحسین، صلاح الدین پرویز کی تخلیقات بین المتونیت کی عمدہ مثال ہیں۔عربی،فارسی اور اردوادب میں تضمین نگاری کی روایت بہت پرانی ہے۔دیوان حافظ اوردیوان غالب کے تمام اشعار کی تضمینیں ہوئی ہیں۔تضمین نگاری خالص بین المتونی عمل ہے ۔اس موضوع پر خاکسار کی ایک کتاب کئی سال پہلے شائع ہوئی تھی۔ ہندوپاک میں کلاسیکی اورہم عصرمتعدد تخلیقات کاتنقیدی مطالعہ بین المتونیت کی روشنی میں کیا جارہا ہے۔
مابعدجدیدیت آفاقیت کے بجائے علاقائیت کوترجیح دیتی ہے اس لیے ادب کا مطالعہ علاقائی اور تہذیبی تناظر میں کیا جارہا ہے۔موجودہ دورمیں قبائلی اورنسلی قصوں ،داستانوںاوردیومالاؤں کے مطالعہ کی اہمیت کافی بڑھ گئی ہے۔نسائی ادب، دلت ادب اور فکشن میں حاشیائی کرداروں کی اہمیت پرکافی زوردیا جاجانے لگاہے۔
عورتوں پرصدیوں سے ظلم وستم اور استحصال کا سلسلہ جاری ہے ، انہیں ہمیشہ مجہول،کمزور اور ناقص العقل سمجھا گیا۔پیشہ ورانہ کارکردگی کے اعتبار سے عورت اور مرد کے درمیان امتیاز کیا گیا۔مذہبی،سیاسی اور سماجی سطح پردونوں کے درجات میں تفریق کی گئی۔پدری نظام،مرد غالب معاشرہ اور مروعورت کے درمیان حقوق کی غیرمساوی تقسیم اور روایات کا جبر جیسے مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ حد تو یہ ہے کہ عورت کو ایک انسان نہیں بلکہ بعض دفعہ اشیا ء یا Commodity سمجھا جاتا رہا ہے۔ شاید اسی لیے Gayle Rubin نے کہا تھا کہ’’عورت شادی میں دان دی جاتی ہے، جنگ میں جیتی جاتی ہے،ہد یہ میں پیش کی جاتی ہے،بطور رشوت دی جاتی ہے اور اسے خریدااور فروخت کیا جا سکتا ہے‘‘۔عورت پر ہونے والے انہیںمظالم کے ردِّعمل کے طور پر تانیثیت کا تصور ظہور پذیر ہوا۔پچھلے دوسوسالوں سے ادبیات عامہ میں تانیثی شعور کی تھرتھراہٹیں موجود ہیں لیکن اس کے واضح نقوش جان اسٹوارمل کی تصنیف “On the subject of women” اور ورجینیاوولف،ایچ۔جی۔ویلز اور برناڈ شاہ کی تخلیقات میں موجود ہیں۔فرانسیسی مفکروں اور قلمکاروں میں جولیا کرسٹیوا،ایلی سیزو،ماریاانتونیتا،Xaviere Gauthier اورSimon de Beauvoir وغیرہ کی تخلیقات میں تانیثی رجحان کی لے مزید تیز ہوگئی ہے۔رفتہ رفتہ تانیثی رجحان مغرب سے مشرق تک پھیل گیااور مشرقی مصنفوں نے بھی اپنی تخلیقات میں تانیثیت کے حق میں کھل کر لکھا۔ہندوپاک کے مصنفوںمیںللّہ عارفہ، مہادیوی،امریتاپریتم،عصمت چغتائی،کملاداس کرشناسوپتی،مہاشویتادیوی،فہمیدہ ریاض،پروین شاکر، کشورناہید، شہنازنبی، فرخندہ نسرین، شفیق فاطمہ،ساجدہ زیدی،سارہ شگفتہ،رفیعہ شبنم عابدی،بلقیس ظفیرالحسن اور عنبری رحمٰن وغیرہ کی تخلیقات میںتانیثی شعوروآگہی بدرجہ اتم موجودہے۔
تانیثیت کے سلسلے میں متعددنقادوں نے بھی اس کے احتجاجی پہلوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا اورسلویاپلاتھ کے اس خیال سے اتفاق کیا کہ ’’عورتوں کے بارے میں گفتگوکی گئی لیکن ان کے لئے گفتگو نہیں کی گئی۔موجودہ دورکے بیشتر ناقدین اور قلم کار تانیثیت کے موضوع پر لکھنے لگے ہیں اوراب تانیثیت نقادوں کااہم موضوع بن چکاہے۔ عورت جنس وصنف کی تفریق، کمتری،جذباتی، عقلی تخصیصات، نسوانی تحریر، مرد کے تئیں اس کا رویّہ ، عورت کا عورت کے تئیں نقطۂ نظر،اس کی عضویت، تفاعلی کردارجیسے موضوعات کو بحث کا موضوع بنایا جارہا ہے۔اس کے علاوہ عورتوں کی زبان کا مسئلہ بھی زیربحث آرہا ہے۔ تانیثی ادب کی معنویت اور نوعیت جیسے امورکی بنیادپرتانیثی نظریے کی تشکیل کی جارہی ہے۔
مختصریہ کہ مابعدجدیدنظریے نے ہمعصر تنقیدی رویے کوکافی متاثرکیاہے۔قاری اساس تنقید مابعدجدیدیت کی سب سے بڑی دین ہے۔اس لیے مابعدجدیددورمیں قاری کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے جس سے ناقدین کے حوصلے بلندہوئے ہیں ۔ مصنف،متن،تناظر،زبان اورقاری میں سے نہ کسی کو حد سے زیادہ نظراندازکیاجارہاہے اورنہ کسی کو ضرورت سے زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے۔لیکن اب دیکھنا ہے کہ ناقدین اپنی تنقیدی ترجیحات میں کس حدتک توازن قائم رکھتے ہیں۔ تنقید میںتوازن اگربرقرار رہتا ہے تو مابعدجدید تنقید کے لیے نیک فال ثابت ہوسکتا ہے لیکن مابعدجدیداصولوں کے مطابق کوئی بھی نظریہ دائم وقائم نہیں ہوسکتاہے ۔اس لیے ممکن ہے کہ جلدہی کوئی نیانظریہ اس کی جگہ لے لے۔
متذکرہ تمام تنقیدی نظریوں کے علاوہ جمالیاتی نظریے نے بھی اردوادب کوکافی متاثرکیاہے۔جمالیات ایک ایسی اصطلاح ہے جس کی تعریف وتوضیح پیش کرنا انتہائی مشکل کام ہے کیوں کہ اس میں اتنی تہیں اور جہتیں پائی جاتی ہیں کہ ان کی تہوں اور جہتوں کو کھولنا اور ان پر روشنی ڈالنے کا کام کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔کوئی ماہرِجمالیات اس کی تہوں کو اتنا ہی کھول سکتا ہے اور اس پر روشنی ڈال سکتا ہے جتنا وسیع اس کا مطالعہ اور مشاہدہ ہوگا۔پھربھی عام طور پر یہ کہاجاتا ہے جمالیات فلسفے کی ایک شاخ ہے جسے حسن، حسن کی فطرت و ماہیت اور فنون لطیفہ سے قریب ترسمجھاجاتا ہے۔بعض ماہرین جمالیات نے اسے فلسفۂ حسن سے بھی تعبیرکیا ہے اور کہا ہے کہ جمالیا ت کاادراک حواس کے ذریعہ ہوتاہے۔لیکن جمالیات دراصل تنقیدکا ایک tool ہے جس کی بدولت فطرت کے جلال و جمال اور فنون کے رشتوں کوسمجھاجاسکتاہے۔ جمالیات’ فنی صداقت‘ اور حقیقت کو سمجھنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ فنون لطیفہ میںجمالیات کی معنویت اپنی تہہ داری کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے ۔ جمالیات ہی تجربہ کو فنی تجربہ بناتی ہے۔ جمالیات سے ہی فن کار کے وژن میں کشادگی پیداہوتی ہے، اس سے فنون لطیفہ میں جلال و جمال کا ایک نظام قائم ہوتا ہے اوراعلٰی درجے کی تخلیق وجودمیں آتی ہے۔
ہندوستان کے قدیم ترین فنون و ادبیات میں جمالیات کی اہمیت بہت زیادہ رہی ہے۔ سنسکرت کے اچاریوں نے حسن، فن اور فنی صداقتوں کو بروئے کارلانے کے لیے ’بھَو‘ یعنی ذہنی کیفیات، ’رَس‘یعنی جلال و جمال، جمالیاتی تجربوں کی فنی ترسیل اور جمالیاتی انبساط یعنی ’آنند‘ کی کیفیت، آہنگ اورآہنگ کی وحدت اور ’النکار‘ یعنی اظہار کے حسن وغیرہ پر جس طرح اظہار خیال کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمالیات کی اہمیت ہندوستانی فنون وادبیات میں کیا رہی ہے۔یعنی جمالیات نے اب جہاں فنونِ لطیفہ کی روح کی گہرائیوں کو سمجھانا شروع کیا ہے وہاں ماضی کے فنون کو دیکھنے کے لیے بھی نیا وژن بھی عطاکیا ہے۔ پروفیسرشکیل الرحمٰن کے مطابق ادب کی تنقید صحیح معنوں میں جمالیاتی ہوتی ہے۔وہ کہتے ہیں کہ ناقد اور فن کار کے جمالیاتی شعور سے جب رشتہ قائم ہوجاتا ہے تو فن کا سچا جوہر سامنے آتا ہے۔ فن کے جلال وجمال کے مظاہر کو محسوس کرنے اور ان کی توضیح و تشریح پیش کرنے کے لیے ناقد کو اپنے جمالیاتی شعور کا سہارا لینا پڑتا ہے ۔پروفیسرشکیل الرحمٰن نے جمالیا ت کی اہمیت ومعنویت پراظہار خیال کرتے ہوئے لکھاہے
’’اس ادبی اصطلاح کی معنویت پھیلتی جارہی ہے اور اس کی نئی جہتیں نمایاں ہوتی جارہی ہیں۔ تاریخی جوہروں سے معمور انسانی اقدار، فن کاروں کی تخلیقات، احساس و ادراک ، کائنات کے جلال و جمال کے مظاہر، شعور و عرفان، آسودگی اور انبساط، پیکر تراشی، آواز اور اس کی گونج، اشاراتی مفاہیم، رمزیت و اشاریت، ڈرامائی خصوصیات، فضا آفرینی، سچائی کی صورت کی تبدیلی، شعوری اور لاشعوری کیفیات، خارجی اور باطنی تحرکات کی وحدت، تخلیقی عمل کی پُر اسرار کیفیتیں، تخیل اور ’وژن‘، تجربوںکا حسن اور تخلیق یا کلام کی آرائش و زیبائش، سب اس کے دائرے اور اس کی گرفت میں ہیں۔ جمالیات کی مدد کے بغیر فنون لطیفہ کا مطالعہ ہی ممکن نہیں ہے۔ جمالیات تو فنون کی روح ہے۔ اس اصطلاح کا سب سے صاف اور واضح مفہوم یہ ہے کہ فن کار کے جمالیاتی شعور نے حیات و کائنات کے جلال و جمال سے کس نوعیت کا تخلیقی رشتہ قائم کیا ہے اور جو تخلیق سامنے آئی ہے اسکا حسن کیا ہے، کیسا ہے۔ ایسی دریافت سے جہاں سماج کے جمالیاتی مزاج اور رجحان کی پہچان ہوتی ہے، وہاں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ فن کار کے جمالیاتی تجربوں نے سوسائٹی کے باطن میں کس نوعیت کی تحریک پیدا کی ہے۔ کبھی کبھی تو فن کاروں کے ایسے تجربوں کے تحرک سے سماج کا مزاج ہی بدل جاتا ہے۔ رجحان اور رویے میں تبدیلی آجاتی ہے‘‘۔
اردو میں جمالیاتی نظریے کوپروفیسرشکیل الرحمٰن نے سب سے پہلے متعارف کرایا اور اس کی اہمیت اور ضرورت پرروشنی ڈالی۔جمالیات کے راستے پروہ اکیلے ہی چلے تھے لیکن لوگ آتے گئے اور کارواں بنتاگیا۔ رفتہ رفتہ جمالیاتی نظریے کواختیار کرنے والے نقادوںکی تعدادمیں اضافہ ہورہا ہے۔ ہندوپاک میںجمالیاتی نظریے کی اہمیت بڑھتی جارہی ہے۔مختلف یونیورسٹیوں میں جمالیات کو تحقیق وتنقیدکاموضوع بنایا جارہا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ صفِ اوّل کے ناقدین میں سے کسی نے بھی اس کی طرف توجہہ نہیں دی۔جب کہ موجودہ دور میں جمالیاتی تنقید کی ضرورت محسوس کی جارہی ہے۔
ہم عصرناقدین میں پروفیسر شکیل الرحمٰن جمالیاتی فلسفۂ ادب،پروفیسرگوپی چندنارنگ مابعدجدیدیت کے فلسفۂ ادب اورشمس الرحمٰن فاروقی جدیدیت کے فلسفۂ ادب کے نہ صرف روحِ رواں ہیں بلکہ نظریہ سازکی اہمیت رکھتے ہیں۔ پروفیسر شکیل الرحمٰن نے جمالیاتی فلسفۂ ادب کی روشنی میں متعدد کتابیں اور تنقیدی مضامین لکھے ہیں جن پرایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے جارہے ہیں۔پروفیسرگوپی چندنارنگ نے نہ صرف مابعدجدید نظریے کی حمایت کی اوراسے وقت کی اہم ضرورت قراردیابلکہ ہم عصرناقدین کی ایک جماعت کی ذہن سازی بھی کی جس سے مابعدجدیدنظریہ تنقید کے موجودہ منظرنامے پرحاوی ہوتاہوا معلوم ہورہاہے ۔وہ اپنے مضامین اورکتابوں میں مابعدجدیدنظریے کااطلاق اکثرکرتے ہیں۔ان کی حالیہ کتاب غالب ،معنی آفرینی ، جدلیاتی وضع شونییتااورشعریات میںانہوں نے اشعار غالب کا مطالعہ تہذیبی تناظر میں کیا اورغالب کوبدھ کے فلسفۂ شونیتا کی روشنی میںنئے سرے سے دریافت کیاہے۔ہم عصرناقدین میںشمس ارحمٰن فاروقی انتہائی ذہین ناقد ، عالم اورجدیدیت کے سب سے بڑے حامی ہیں، اپنی غیرمعمولی صلاحیت کی بدولت اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔لیکن مابعد جدیدناقدین نے ان کی متعددتحریروں اورعبارتوں کی روشنی میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مابعد جدیدیت کے سب سے بڑے مخالف ہونے باوجودان کی نگارشات میں مابعدجدیدیت کی گونج سنائی دیتی ہے ۔مابعد جدید ناقدین کی رائے سے اتفاق کیاجاسکتاہے لیکن اس سے شمس الرحمٰن فاروقی کی عظمت کم نہیں ہوسکتی ہے۔کوئی بھی بڑاناقد چاہے کسی بھی نظریے کی حمایت کرے لیکن وہ کسی خاص نظریے کا تابع نہیں ہوسکتا ہے۔وہ نظریے کے تمام دائرے کو توڑکر باہر نکل جاتا ہے۔بڑاناقد نظریۂ علم‘‘ یا’’ علمیات‘‘کے تمام Tools مثلاً زبان کا علم، روایت کی آگہی،شعریات کی آگہی اورفلسفۂ ادب یانظریاتی آگہی سے باخبرہوتاہے اورتنقیدی عمل کے دوران نظریے سے زیادہ اپنی نظرپربھروسہ کر تا ہے۔ نظریے کوغیرضروری اہمیت دینااورکسی خاص نظریے کومذہبی فریضہ سمجھ کراپنی تحریروں میں اطلاق کرتے رہنا تنقید کے لیے صحت بخش نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو بڑے ناقدوںمیں شمار نہیںکیاجاسکتاہے۔موجودہ دورمیں جو ناقدین ادبی منظرنامے پر چھائے ہوئے ہیں ان میں پروفیسر عتیق اﷲ،پروفیسرشمیم حنفی اورپروفیسر ابولکلام قاسمی تنقیدکے تمام حربوںاور نظریوں سے باخبر ہیں لیکن کسی خاص نظریے کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔پروفیسرعتیق اﷲنے مابعد جدید نظریے کے مختلف شقوں مثلاًتاریخیت اورنوتاریخیت،تانیثیت،ساختیاتی اور پس ساختیاتی نظریے پرمضامین لکھے ہیں پھربھی انہیں مابعدجدید تنقید نگاروں میں شمار نہیں کیاجاسکتاہے کیوں کہ ان کاتنقیدی رویہ مابعدجدیدنظریے کے تابع نہیں ہے۔شمیم حنفی کوبھی جدیدیت سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے لیکن وہ بھی کسی نظریے کے اسیرنہیں ہیں ۔پروفیسرابوالکلام قاسمی اگرچہ مشرقی تنقیدی روایت کے امین ہیں لیکن وہ مابعدجدیدنظریے کی بھی حمایت کرتے ہیں ۔ اس کی وجہ شایدیہ ہوسکتی ہے کہ مابعد جدیدیت کی جڑیں مشرقی شعریات میں کافی گہری ہیں اس لیے قاسمی کاذہن جلدہی مابعدجدیدنظریے سے ہم آہنگ ہوجاتاہے پھربھی انہیں مابعدجدیدناقدوں میں شمار نہیں کیاجاسکتا۔پروفیسرعتیق اﷲ ،پروفیسر شمیم حنفی اورپروفیسرابوالکلام قاسمی کی تنقیدی نگارشات کا مطالعہ کرتے وقت محسوس ہوتا ہے کہ تمام ادبی نظریے،شعریات اور تہذیبی وراثت ان کے ذہنوں میں محفوظ ہیں جن کا استعمال حسبِ ضرورت کرتے ہیں۔ اس لیے ان ناقدین کوبین العلومی نظریات یا متبادل نظریۂ تنقید کے حامی نقادوں کے گروپ میں رکھاجانا چاہئے۔تنقیدکے منظرنامے پرایک اوراہم نام پروفیسرحامدی کشمیری کاہے جنہوںنے ادبی تنقیدمیںاکتشافی تنقیدکے نظریے کوپیش کیااورعملی طورپراپنی نگارشات میں اس کااطلاق کرکے تمام نظریہ سازوں اورناقدین کوچونکادیا۔ہم عصرناقدین کی فہرست بہت لمبی ہے لیکن مابعدجدیدناقدین میں ناصرعباس نیّر، شافع قدوائی،نظام صدیقی، قاضی افضال، خالدقادری اور الطاف انجم وغیرہ کے نام بطور خاص لیے جاسکتے ہیں کیوں کہ یہ تمام ناقدین صاحب کتاب ہیںاورجن کے مضامین مسلسل شائع ہو تے رہتے ہیں جن میں مابعدجدیدنظریے کااطلاق بطورخاص کیاجاتاہے۔ ترقی پسند اورجدیدیت کے نظریے کی روشنی میں ہنوز مضامین لکھے جا رہے ہیں اوران نظریوں کے وجودکوبرقراررکھنے کے لیے کوششیں بھی کی جارہی ہیں۔جس سے نظریاتی تصادم کی صورتِ حال پیدا ہوگئی ہے۔لیکن موجودہ دورمیں ایسے ناقدین کی تعدادبہت زیادہ ہے جن کا تعلق کسی بھی مکتبۂ فکریا نظریات یاادبی گروہ سے نہیں ہے اور جوبنا تفریق وتعصب مسلسل مضامین لکھ رہے ہیں اور جو ادبی منطرنامے پراپنی موجودگی درج کراچکے ہیںان میںپروفیسرقدوس جاوید،پروفیسر انیس اشفاق ،سلیم شہزاد ، پروفیسرخورشیداحمد، پروفیسرقاضی جمال ،بیگاحساس،پروفیسرمناظرعاشقہرگانوی،پروفیسرانورپاشا،آفتاب احمدآفاقی،ابوبکرعباد،کوثرمظہری،احمدامتیاز،ارشادنیا زی،جمال اویسی، حقانی القاسمی وغیرہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔یہ وہ ناقدین ہیںجو تنقیدکے تمام حربوں سے بھی واقف ہیں۔
بعض نظریہ ساز ناقدین کا خیال ہے کہ نظریے کے بغیر تنقید ممکن ہی نہیں ہے لیکن ایسے خیالات سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا ہے کیوںکہ زبان میں نظریہ پہلے سے موجود ہوتاہے ۔اس لیے وہ ناقدین جن کاتعلق کسی نظریے سے نہیں ہے ان کی تنقیدمیں نظریہ موجود ہوتا ہے لیکن وہ کون سا نظریہ ہے اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔لیکن اگران نظریوں کی پہچان کر بھی لی جائے تویہ فیصلہ کرناناممکن ہے کہ ان میں سے کون سا نظریہ تنقیدی منظرنامے پرغالب ہے؟اسی لیے موجودہ دور میںادبی تنقید کے مقاصد اورطریقوں پرغیرمعمولی اختلافات پیدا ہورہے ہیں کیوں کہ موجودہ دورمیں بے شمار تنقیدی نظریات رونما ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ناقدین ادبی تھیوری یانظریے کے علاوہ برِاعظم کے فلسفوں میں بھی کافی دلچسپی لے رہے ہیں۔ بعض ناقدین بڑی حد تک نظریاتی قطعیت کے ساتھ کام کررہے ہیں جبکہ دوسرے روایتی ادب کامطالعہ کررہے ہیں اور ادبی فلسفے میں دلچسپی لے رہے ہیں لیکن بہت سے ناقدین اقلیتی یادلت اور تانیثی ادب میں دلچسپی لے رہے ہیں۔بعض ناقدین تہذیبی مطالعہ سے متاثرہیں اورPopular ادب پڑھ رہے ہیں۔بعض ناقدین تاریخیت اور نوتاریخیت کو زیربحث لا رہے ہیں۔ماحولیاتی ناقدین نے نیچرل سائنس اور ادب میں رشتہ قایم کیاہے اور ادب میں ماحولیات بھی زیرِ بحث آرہے ہیں۔اب اس کثیر نظریاتی دور میں ناقدین کو انتخاب کرناہوگاکہ کس نظریے کو اختیار کیا جائے اور کسے ترک کیاجائے یا بین العلومی نظریے کی روشنی میں تنقیدی فرائض کا کام انجام دیاجائے۔