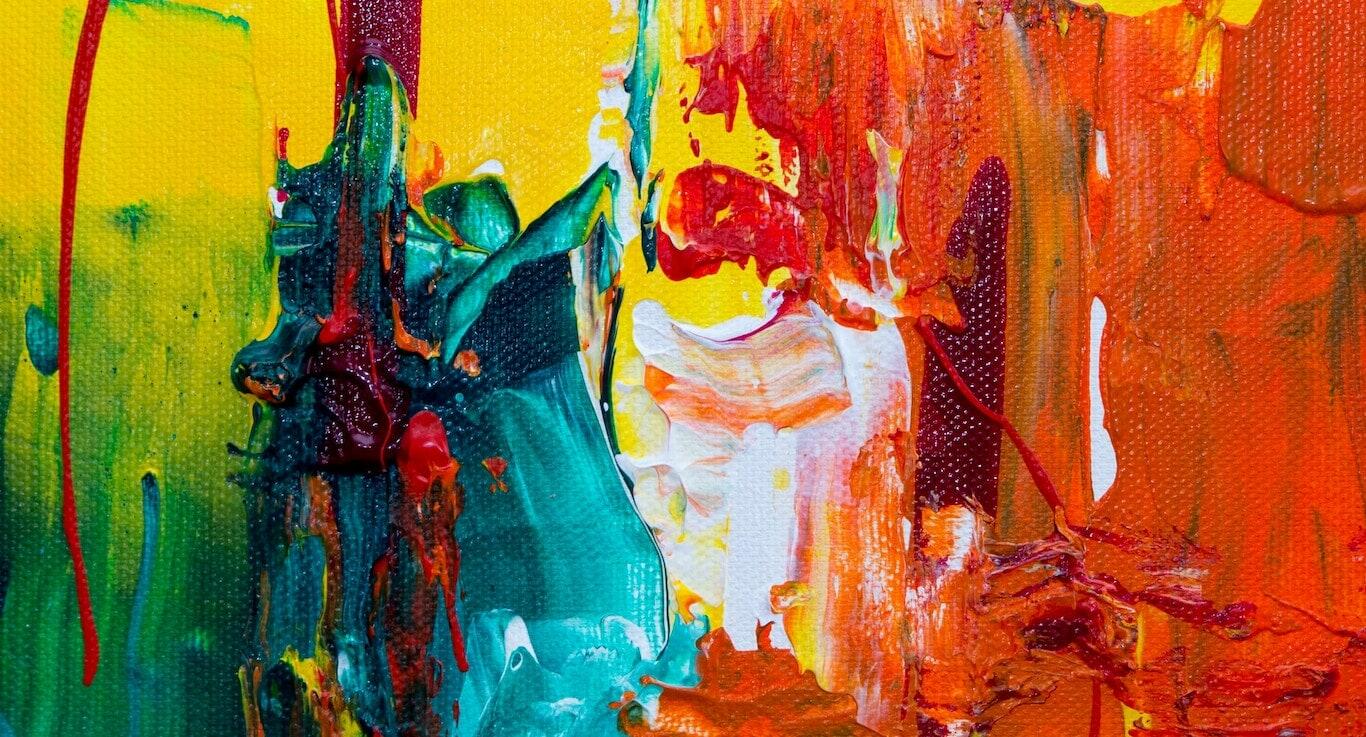نوٹ
پروفیسر شکیل الرحمٰن صاحب پر میرا مضمون’’شکیل الرحمٰن کا بوطیقا ‘‘جب شائع ہوا توپروفیسرسیدہ جعفر صاحبہ نے اسے پڑھ کرشکیل الرحمٰن صاحب سے اس کی تعریف کی۔اس کے بعد شکیل الرحمٰن صاحب نے سیدہ جعفرصاحبہ کے مضامین کاایک مجموعہ مجھے بھیجا اور ان پر ایک مضمون لکھنے کا حکم دیا۔ لہٰذا یہ مضمون پروفیسر شکیل الرحمٰن صاحب کی فرمائش پر لکھا تھا۔ عجیب اتفاق ہے کہ 9مئی 2016 کو شکیل الرحمٰن صاحب کا انتقال ہوگیا اور ٹھیک ماہ 15 دنوں کے بعد یعنی 24 جون 2016 کو پروفیسرسیدہ جعفر صاحبہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ خدا دونوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔
سیدہ جعفر فلسفیانہ تنقید اور شگفتہ بیانی
ناقدین کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں اور تنقیدی رویے ہیں۔ بعض تنقیدنگار اپنے رویے اور رجحان کے حصار میں ہی قید ہوجاتے ہیں، کچھ اس حصار سے باہرنکل آتے ہیں۔ سیدہ جعفر کا شمار آخرالذکر میں ہوتاہے۔ ان کے تنقیدی رویے میں امتزاجیت کا عنصر ہے۔نقد کے تمام رویے اوررجحانات پران کی گہری نظر ہے۔
سیدہ جعفر مشرقی شعریات(سنسکرت جمالیات، عربی،فارسی اورکلاسیکی اردوادب کی تنقید) سے شروع کرکے رومانی تنقید (صوفیانہ اور فلسفیانہ ادب کی تنقید کے حوالے سے)، مابعد جدید تنقید، اکتشافی تنقید اور تانیثی تنقیدوغیرہ سے متعلق مباحث میں اپنے تنقیدی جوہر کامظاہرہ کرچکی ہیں۔ اب تک تیس کتابیں اور بیسیوں مضامین شائع ہوچکے ہیں جوان کے تنقیدی تحرک کا ثبوت ہیں۔
پروفیسرسیدہ جعفرکا تنقیدی اندازِفکر فلسفیانہ معلوم ہوتا ہے۔انہوں نے ایک مضمون’’قرۃ العین حیدرکا تصوّروقت ‘‘میں فکشن کی مشہور تکنیک’’شعور کی رو‘‘ کو وقت کے فلسفیانہ تصور سے وابستہ کیا ہے جس میں ’وقت‘ گھڑی کے نظام کے تابع نہیں ہے بلکہ اقبال کے لفظوں میں ’’ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات‘‘۔یعنی وقت تعینات سے ماوراہے کیوں کہ(بقول اقبال) ہماری یہ بیکراں دنیاوقت کے بحر ذخار میں مثل ایک ماہی نیم تاب کے تیرتی پھر رہی ہے۔حدیث قدسی بھی ہے کہ’’زمانے کو برا نہ کہو کہ میں ہی زمانہ ہوں‘‘۔ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم نے فکر اقبال میں لکھاہے کہ’’ اقبال زمانہ کو مجردوساکن نہیں سمجھتا بلکہ یہ ایک تخلیقی حرکت کا نام ہے۔سیدہ جعفر نے قرۃ العین حیدرکے تمام ناولوں میں موجود شعور کی رو پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کا اطلاق وقت کے اسی تصور پر کیا ہے۔اپنی باتوں میں اور دلیلوں میں زور اورتوانائی پیدا کرنے کے لیے علامہ اقبال برگساں اور دوسرے مغربی فلسفیوں کے حوالوں کی روشنی میں تصور وقت کے موضوع پر جس طرح سیدہ جعفر نے بحث کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تنقیدی رویہ فلسفیانہ اور مطالعہ وسیع ہے۔
سیدہ جعفر نے ’’غالب محشر خیال‘‘میںاس بات پر زور دیا ہے کہ غالب نے فلسفے کے کسی مخصوص پہلو پر اصرارنہیں کیا ہے پھر بھی انہوں نے غالب کی شاعری میں موجود فلسفیانہ عناصر پر تنقیدی بحث کی ہے۔انہوں نے غالب کی شاعری کے متعلق یہ کہہ کر ’’غالب کی شاعری حیات کی رمزشناسی میں مضمر ہے‘‘یا ’’تصوف غالب کا ایک اندازفکرتھااوروہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس زاویئے اور اس سطح سے زندگی کیسی نظرآتی ہے خود اپنے تنقیدی رویہ کوواضح کردیا ہے۔کیوں کہ حیات کے رمزشناس یا تصوف کے زاویئے سے زندگی کا مشاہدہ کرنے والے شاعر کافلسفی اور اس موضوع کوزیربحث لانے والا ناقد کاapproach فلسفیانہ ہونا لازمی ہے۔انہوں نے غالب کی شاعری میں مختلف سمتوں میں پھیلے ہوئے سوالات،تشکیک،استعجاب اور تلاش وجستجو کے میلانات پر جس طرح اظہار خیال کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تنقید کی واضح رجحان کیاہے۔سیدہ جعفر کا خیال ہے کہ غالب نے بھی تجسس کی مدد سے زندگی کی راز کو سمجھ لیا تھا انہوں نے لکھا ہے
’’ زندگی کی اصل حقیقت تغیر مسلسل اور دائمی گریزپائی اورسیمابیت ہے۔زندگی کا سفر مسلسل ہے مناظر بدلتے رہتے ہیں اور ان کی تبدیلی کی سرعت سے سفر کی حقیقت اور اس کے مقاصد میں تبدیلی نہیں آتی۔عمل اور ردعمل، حرکت وسکون اورمتضاد محرکات کی کارفرمائی زندگی کی تکمیل اور اس کی سا لمیت کا اظہار ہے۔‘‘(تفہیم وتجزیہ، ص- 282 )
سیدہ جعفرکے فلسفیانہ بیانات سے ان کی سوچ کی کڑیاں یونانی فلسفیوںسے ملتی ہیں۔یونانی فلسفیوں کے مطابق فلسفہ میں جس قدر سوال پیدا ہوتے رہتے ہیں اسی قدر اس کی جانب سے اطمینان بخش جوابات کا امکان پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس طرح فلسفہ زندہ رہتا ہے اور پنپتا ہے۔افلاطون نے بھی فلسفہ کے دائرہ کار کو حیرت پر منطبق کیا تھا۔اس نے اپنی مشہورزمانہ تصنیف Theaetetus میں لکھا ہے کہ حیرت کا جذبہ کسی بھی فلسفہ کے لئے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔کیوں کہ فلسفیانہ تفکر کے لئے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نقطۂ آغاز موجود نہیں۔سیدہ جعفر نے غالب کی شاعری پر بحث کرتے ہوئے انہیں نکات کی طرف اشارہ کیاہے ۔اس کی مزیدوضاحت ایک دوسرے مضمون ’’کلام غالب کی آفاقیت‘‘ میں آئنسٹائن کے حوالے سے بھی کی ہے
’’جرمنی کے مفکر آئنسٹائن نے کہا تھا وہ انسان جو کائنات پر اظہار تعجب کے لئے نہیں ٹھہرتا اور اس پر تقویٰ کی کیفیت طاری نہیں ہوتی وہ مر چکا ہے اور اس کی آنکھیں بصارت سے محروم ہیں۔خالق ومخلوق کی حقیقت میں ایک ازلی اور ابدی رشتہ موجود ہوتاہے اور صوفیاء کی نظر لاموجودالااﷲکاجلوہ دیکھتی ہے ‘‘(تفہیم وتجزیہ، ص- 282 )
سیدہ جعفر نے انسانی وجود اور کائنات کے متعلق غالب کے اشعار پر اظہارخیال کرتے ہوئے وجود کی شیرازہ بندی کے لئے فناوبقا، حیات وممات ، نوروظلمت اورتعمیروتخریب جیسے متضاد حقیقتوں کو لازم وملزوم قرار دیا ہے۔اپنی بات کو مدلل بنانے کے لیے ارسطوکے اس تصوّر کو پیش کیا ہے جس میں اس نے ہیولیٰ اور صورت کو لازم وملزوم قرار دیا تھاجس کی تائید جرمن فلسفی ہیگل نے بھی کی تھی۔
تانیثیت جدید تنقیدکا اہم موضوع ہے۔سیدہ جعفر نے اس موضوع پر اپنی منفرد شناخت قائم کی ہے۔انہوں نے اپنے مضمون’’اردو ادب میں تانیثیت کا رجحان‘‘ میں تانیثیت کے کثیرالمعانی جہات اور اس رجحان کے وجود میں آنے کے وجوہات پرجس طرح روشنی ڈالی ہے اور اس کے آغازوارتقا میں جن مفکرین کے حوالے دیئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اردوادب میں تانیثیت کے رجحان کو فروغ دینے میں ان کا اہم رول رہا ہے۔اردو کے تانیثی ادب کے فروغ میں جن خواتین تخلیق کاروں نے حصہ لیاہے ان کی تخلیقات کی روشنی میں عورتوں کو موجودہ سماجی نظام سے برسرِ پیکار ہونے،روایت کو توڑنے، مروجہ نظام کورد کرنے اور سماج میں اپنی شناخت قائم کرنے کی آرزؤں کی وضاحت کی ہے۔عورتوںکی حمایت میںانہوں نے اپنے مضمون میں The First Sex جیسی کتابوں کے اقتباسات کوٹ کرکے دماغی ساخت اور زبان کے اعتبار سے عورت کی اہمیت کومسلّمہ قرار دیا ہے۔
ہیلن فشرکے بیانات کی تائید کرتے ہوئے انہوں نے اپنے موقف کا اظہار کردیا ہے کہ ادب کے موجودہ منظر نامے میں خواتین تخلیق کاروں کی ازسرنوقدرشناسی اور تنقید کے مرد غالب رجحان میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔اس سے تانیثیت کے متعلق ان کے نظرئے کی وضاحت بھی ہوتی ہے۔
سیدہ جعفر کی تنقید میں رومانیت کی آمیزش کا بھی احساس ہوتا ہے۔انہوں نے فیض احمد فیض کی شاعری کا امتیازی وصف ان کی شاعری میں موجود حقیقت اور رومانیت کا حسین مرقع قرار دیا ہے۔سیدہ جعفر کے مطابق فیض احمد فیض کی شاعری کا خمیرسرفروشی اور رومانیت کے اتصال سے اٹھا ہے جس سے فیض کے شاعرانہ مسلک کی دورنگی نہیں جامعیت کا اظہار ہوتا ہے۔انہوں نے فیض کی شاعری میں اس حصّے کو بہتر اور جاندار قرار دیا ہے جس میں شاعری خطابت کے بجائے دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی آواز معلوم ہوتی ہے۔اس بیان سے سیدہ جعفر شاعری میںکلاسکی اصول وضوابط کی پیروکارمعلوم ہوتی ہیں کیوں کہ 12 صدی ہجری کا عالم عروض شمس قیس رازی نے بھی ہرن اور شکاری کتّے کی تمثیل کوبیان کرنے کے بعد کہا تھا کہ شاعر کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آوازشعر کی اصل روح ہے جو سننے والے کے موڈ کوبدل دے۔
سیدہ جعفر نے فراق کی شاعری اورخاص کر ان کی رباعیوںپر اظہار خیال کرتے ہوئے ہندوستان کی ہزاروں سال پرانی تہذیب ، سنسکرت جمالیات اوردکنی ادب پرجس طرح سے روشنی ڈالی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ادب کا مطالعہ تہذیبی پس منظر میں کرتی ہیں۔وہ ہندوستان کی قدیم شعری روایت اور تہذیب سے انحراف کی قائل نہیں ہیں ۔ ان کا خیال ہے کہ ہندوستان کی پرانی تہذیب اورقدیم شعری روایت سے رشتہ قائم رکھتے ہوئے ادب کی تخلیق جدیدتقاضوں کے مطابق کرنی چاہئے۔ان کا خیال ہے کہ فراق کی شاعری بعض عروضی کوتاہیوں کے باوجود مقبول ومشہور ہوئی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فراق کی شاعری کی جڑیں ہندوستان کی ہزاروں سال پرانی تہذیب سے جا ملتی ہیں۔اسی لیے فراق کی شاعری میں ہندوستان کی مٹّی کی سوندھی سوندھی خوشبوکا احساس ہوتا ہے۔ فراق کے یہاں جنس کا جذبہ اکثر عشق کی بھٹی میں تپ کرنکھرگیاہے لیکن بقول سیدہ جعفر’’کلام فراق میں جہاں جنسی جذبے کوعشق کی بھٹی میں تپ کر کندن بننے کا موقع نہیں مل سکا اور جہاں وہ تخلیقی حسیت سے پوری طرح ہم آمیز نہیں ہو سکا ہے، فراق کے اشعار کی شعری توقیر پر آنچ آگئی ہے‘‘۔انہوں نے اپنی بات کی تائید میں فراق کا بیان کوٹ کیا ہے
’’جنسی یا شہوانی محرکات کا شعر میں اظہار عموماً عشقیہ شاعری سمجھا جاتا ہے ۔لیکن جس طرح کوئلہ کو ہیرا نہیں سمجھاجاتااگرچہ کوئلہ مدت دراز میں آفتاب کی تابندگی اپنے اندر جذب کرکے ہیرا بن جاتا ہے۔اسی طرح شہوانی اورجنسی جذبہ بھی جب تک عشق کے عناصر اپنے اندر جذب نہ کرلے عشقیہ جذبہ نہیں کہلاتا‘‘(کتاب نما،اگست 2010 ، ص- 16 )
سیدہ جعفر کے مطابق دکنی ادب میں قدیم ہندوستان کی لوک کتھاؤں، لوک گیتوں اور اساطیری علامتوں کے جو تصورات ہیں وہ تصورات فراق کی شاعری میں بھی موجود ہیں۔ فراق کی شاعری قاری کے دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے کیوں کہ ہم سب صدیوں سے اسی تہذیبی اور جمالیاتی تصورات سے ذہنی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔فراق کی شاعری میںزیر بحث خصوصیات کی بنا پر سیدہ جعفر نے انہیں شرینگاررس اورجمالیاتی شعور کا فنکار قرار دیا ہے۔ماہر سنسکرت جمالیات ابھینوگُپت کے حوالے سے ’’سرینگاررس ‘‘اور ’’رتی بھَو‘‘کی تعریف وتوضیح سیدہ جعفر نے پیش کی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سنسکرت جمالیات سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ان کا خیال ہے کہ شرینگار رس کا پہلا بھاؤ رتی بھاؤفن اور ادب میں سرایت کرکے انہیں لمسیاتی آب ورنگ اور جمالیاتی حس یعنی ’’سوندریا بودھ‘‘عطا کرتے ہیں۔ ’’سوندریا بودھ‘‘کی اصطلاح پر اظہار خیال کرتے ہوئے ’’ستیم شیوم سندرم‘‘کے تصور کوعظیم اور آفاقی شاعری کا درجۂ کمال مانا ہے۔سیدہ جعفر نے شاعری میں آہنگ،موسیقی اور رقص کی آمیزش سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے بہترین شاعری قرار دیا ہے۔ہندوستانی فکریات کے آئینے میںانہوں نے کہا ہے کہ دنیانٹ راج یعنی شیو جی کے رقص سے قائم ہے۔سرینگار رس پر رقص کے اثرات کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے انہوںنے کیا خوب لکھا ہے کہ’’رومانی فکر’’سوندریا آنند‘‘ سے مستفیدہوتی ہے تورقص اور سنگیت کی توانائی سرینگاررس کے نشاط وانبساط کووسعت اور تعمق عطاکرتی ہے۔ ‘‘مختصر یہ کہ شاعری کے لئے وہ لفظوں کے آہنگ اورزیروبم کو ضروری سمجھتی ہیں کیوں کہ لفظوں کے آہنگ اور زیروبم سے شعر میں موسیقیت پیدا ہوتی ہے اور ہندوستانی طرزفکرکے اعتبار سے موسیقی کائناتی حسن کار مز ہے۔اسی لئے سیدہ جعفر نے حضرت امیرخسرو کے بیان سے اتفاق کیا ہے کہ ہندوستانی موسیقی ایک آگ ہے جوقلب ونظر کوجلاتی ہے۔ان کا یہ خیال بھی بہت بلیغ ہے کہ ایک نقطے پر پہنچ کرفنون لطیفہ میں سنگیت اور رقص کافن ایک دوسرے کے بہت قریب آجاتے ہیں کیوں کہ ان میں ایک داخلی ربط موجود ہوتا ہے۔ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے فراق کی شاعری کے متعلق ان کا یہ بیان کہ’’فراق نے نغمہ آہنگ اور جمالیاتی حس کے جو پیکرتراشے ہیں وہ دلفریب اورنظرنواز ہی نہیں شعوراوراحساس کی گہرائیوں میں اتر جانے والی امیج ہے‘‘کتنامعنی خیز ہے۔فراق کی شاعری میں رات کی کیفیت نے سیدہ جعفر کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے ۔اس لئے انہوں نے رات کی کیفیت پر بھی عالمانہ بحث کی ہے۔انہوں نے فراق کو شب گزیدہ شاعر قرار دیا ہے اورکہا ہے کہ رات کی کیفیتیں اور رات کی رمزیت جس طرح فراق کے اشعار میں فضا باندھتی ہیں وہ کہیں اور نہیں ملتی۔انہوں نے رات کی کیفیتوں اور رنگینیوں کے متعلق فن مصوری کے ماہرین کے حوالے سے لکھا ہے
’’دن میں اتنے رنگ نظر نہیں آتے جتنے رات میں دکھائی دیتے ہیں۔آمدشب کے اہتمام سے ابتدا کیجئے توشفق کا سنہری،نارنجی،زردی مائل کبود،سرخ اور نیلگوں رنگ،رات کا سرمئی اور سیاہ رنگ،چاندنی کی دلفریب اور اجلی رنگ۔یہ تمام رنگ اپنی مخصوص کیفیات اور تاثرات کے ساتھ انسان کے جذبات پر اثراندازہوتے ہیں۔رنگوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔جس کی ترسیلی توانائیوںسے مصوراور شاعرزیادہ اثر پذیر ہوتے ہیں‘‘۔(کتاب نما،اگست 2010 ، ص- 10 )
اس بیان کی روشنی میں وہ کہتی ہیں ’’رات کا سناٹا،اضطراب،’’دیدۂ نمناک‘‘میںلہراتا ہوا کوئی پیکرِواہمہ(Fantasy )اورتصور کے پردے پرنظرآکے چھپ جانے والی معطر پرچھائیں،یہ شبِ فرقت کا قیمتی اثاثہ ہے‘‘۔ رات کی کیفیت کے حوالے سے سیدہ جعفر نے فراق کی شاعری کا معنیٰ خیزتجزیہ کیا ہے۔
جمالیاتی تنقید میں بھی سیدہ جعفرکودسترس حاصل ہے۔اپنے ایک مضمون ’’جمالیاتی آگہی کا مصنفشکیل الرحمن‘‘میں جمالیات کے موضوع پراظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ جمالیات، فلسفہ کا ایک شعبہ ہے۔انہوں نے ادب اور جمالیات کے درمیان جورشتہ ہے اس کی تفہیم کا تعلق دانشوری اور تنقیدی شعور سے کیسے ہے،جمالیات کا پہلا مفکربام گارٹن نے فنون لطیفہ میںجمالیات کے تفاعل اور اس کے دائرہ کار کی وسعتوں سے کیانتیجہ اخذ کیا،اسی طرح ہیگل نے حسن اور حسن کاری کے وسیلے سے جمالیات کامطالعہ کیسے کیا وغیرہ اہم موضوعات سے بحث کی ہے ۔انہوں نے اس حقیقت کی طرف بھی اشارے کیے ہیں کہ مختلف محرکات، ماحول، ذہنی تربیت اور افتادطبع کے زیر اثرہوتے ہیںاس اثر آفرینی کے درجات متعین کئے جاتے ہیں۔ انہوں نے جمالیات سے بحث کرتے ہوئے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ مختلف علاقوں کی تہذیبی روایت کے زیراثر جمالیات کا تصوربدلتا رہتا ہے مثلاًجنوبی ہندوستان میں بت تراشی کے نادر نمونوں میں بدن کا گداز اور ان کی گولائی، ایران میں بلندی ، نفاست اورمحبوب کے لئے صنوبر کا استعارہ، افریقہ میں سیاہ رنگ،موٹے ہونٹ اور چپٹی ناک والی محبوبہ جمالیات کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی مانی جاتی ہیں۔
سیدہ جعفر نے اردو کے ماہر جمالیات شکیل الرحمن کی تخلیقات کی روشنی میں ان کی جمالیاتی تنقید کا جائزہ لیا ہے اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ شکیل الرحمن نے فنون لطیفہ (مثلاً موسیقی، رقص،سنگ تراشی،فن تعمیر اور شاعری) میںجمالیات کی جو تفہیم وتعبیر پیش کی ہے اس سے ان کی شناخت ایک ماہر جمالیات یا جمالیاتی آگہی کے مصنف کی شکل میں ہوجاتی ہے۔
شکیل الرحمن کی جمالیاتی تنقیدکے مختلف پہلوؤں پر متعدد دانشوروں، فلسفیوں اور مختلف علوم کے ماہرین کے تصورات اور اقتباسات کے حوالے کی روشنی میں جس طرح تفصیل سے سیدہ جعفرنے مدلل اظہار خیال کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمالیاتی تنقید پر بھی ان کی نظرعمیق ہے۔
سیدہ جعفر نے برطانوی نژادفکشن نگارSomerset Maugham کے فکروفن پر اظہار خیال کرتے ہوئے اسے انسانی فطرت اورنفسیات کے پیچیدہ اور حیران کن رموزکوآشکار کرنے والافنکار قرار دیا ہے۔انہوں نےSomerset Maugham کے ایک ناول”Moon and six pence”میں آرٹ،عورت،محبت،اخلاقی ضوابط اور سماج کے متعلق اپنے خیالات کا اظہارکیا ہے۔ اس ناول کے ہیرواسٹرک لینڈاور اس کی بیوی کے درمیان کے تعلقات پرتبصرہ کرتے ہوئے ازدواجی زندگی کی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کبھی کبھی انسان ازدواجی زندگی میں شب وروز ایک دوسرے کی محبت میں بسر کرنے کی وجہ سے دونوں اپنی شخصیت کی جاذبیت اور کشش سے محروم ہونے لگتے ہیں۔سیدہ جعفر نے اسے انسانی نفسیات کی بوالعجبی اور انسانی جذبات کے ایک عجیب وغریب تفاعل سے تعبیر کیا ہے۔انہوں نے Somerset Maugham کے اس ناول کا مقابلہ ہندی کے فکشن نگارگل شیرخان ثانی کی تخلیق ’’آنکھیں‘‘ سے کیا ہے اور اس کی روشنی میں لکھا ہے کہ
’’انسان فطرتاً تازگی پسند واقع ہوا ہے۔ازدواجی زندگی میں کبھی کبھی گزرتے ہوئے ماہ وسال تازگی مٹا کر جذبے کو پژمردہ اورحس کو کند کردیتے ہیں اور زندگی میں یکسانیت اور بے کیفی کا احساس شدید ہونے لگتا ہے۔اس لیے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے بھی فریقین جذباتی طور پر دور ہوجاتے ہیں‘‘۔(اردو دنیا،مئی 2010 ،ص- 21 )
Somerset Maughamکے اس ناول کا ہیرواسٹرک لینڈجو ایک مصور تھا اپنی بیوی کوچھوڑ کر South seas چلا جاتا ہے اور اپنے کاٹج کی دیواروں پر جنت کی تصویر کھینچ کر اپنے آرٹ کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن اس کی موت کے بعد اس کے کاٹج کو آگ کے سپردکردیا جاتا ہے۔سیدہ جعفر نے اس کے شاہکار آرٹ کی تعریف وتجزیہ کرتے ہوئے رنگوں اورتصویروں کو لفظوں کے مقابلے میں بہتر اظہار کا ذریعہ قرار دیا ہے ۔اس سلسلے میں نقادوں اور کہاوتوں کے حوالے سے لکھا ہے
’’آرٹ کے بعض نقادوں کا خیال ہے کہ تصویرمیں لفظ سے زیادہ گویائی اورقوت ترسیل موجود ہوتی ہے۔ انہوں نے لفظ پر رنگ کوترجیح دی ہے۔ایک قدیم چینی کہاوت ہے کہ ایک تصویر دس ہزار الفاظ سے زیادہ موثر ہوتی ہے۔رفائیل، قاسم،میرک،عبدالرحمن چغتائی، صادقین اورمقبول فداحسین کا آرٹ اپنی تاثرآفرینی کی وجہ سے اہلِ نظرکے دل کی دھڑکن بن گیا ہے۔‘‘(اردو دنیا،مئی2010 ،ص- 21 )
سیدہ جعفر اعلیٰ درجے کے اشعار کی تخلیق کے لئے علامتوں کے استعمال کو ضروری سمجھتی ہیںان کا خیال ہے کہ یہ شعر کی قدروقیمت کی کسوٹی بھی ہے۔انہوں نے بجا کہا ہے کہ دوسرے اصناف کے مقابلے میں غزل کے اشعار میں علامت کی اہمیت زیادہ ہے کیوں کہ اس کی تہداری،رمزیت اور لچک نئے نئے مفاہیم کے دروازے کھول دیتی ہے۔انہوں نے فرائڈ،ولیم جیمز،پرل اور مرفی جیسے مفکرین کے اقتباسات کی روشنی میں علامت کو ایک وسیع اور ہمہ گیرادبی پیکر سے تعبیر کیا ہے جس کی وسعتوں میں دوسری شعری حقیقتیں جذب ہوجاتی ہیں۔اسی لئے ان کا خیال ہے کہ قاری شاعر کے ذریعہ استعمال کی گئی علامتوں سے نئے مفاہیم ومعنی کی ایک دنیا آباد کرسکتا ہے۔مثال کے طور پر انہوں نے غالب کی شاعری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ غالب لفظیات کا رشتہ نئے علامتی ادراک اور نئی شعری آگہی سے جوڑ دیتے ہیںتو غالب کی عظمت کے نئے پہلوروشن ہونے لگتے ہیں۔انہوں نے William york Tindall کی کتاب The literary symbol کے حوالے سے علامت کی معنویت کو قاری کی حسیت اورذہانت کا رہین منت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اسی وجہ سے جدید دور میں شاعری کے مطالعے کی نوعیت Reader Oriented ہو گئی ہے۔
سیدہ جعفر نے اسلوبیاتی تنقید کے ناقدین مسعود حسین خان، مغنی تبسم، مرزا خلیل بیگ اور گوپی چند نارنگ کے تصوّر تنقید پر سیر حاصل بحث کی ہے۔انہوں نے اردو میں اسلوبیاتی تنقید کے بانی مسعود حسین خان کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسعودحسین خان نے تنقیدمیںمتن کی کلیدی اور بنیادی اہمیت کا احساس دلایا ہے ۔انہوں نے اقبال، غالب اور فانی کے کلام کا تجزیہ جس نظریے کے تحت پیش کیا اس سے انہیں جدید ہیئیتی تنقید اور ادبی اسلوبیات کا بانی تصوّرکیا گیا۔انہوں نے شعر کی معنیاتی سطح تک پہنچنے کے لیے اس کی صوتی،صرفی اور نحوی سطحوں سے گذرکر ان کا تجزیہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔سیدہ جعفر نے مسعود حسین خان کے اس بیان سے اتفاق کیا ہے اور دلیل یہ دی ہے کہ علمائے بلاغت شعر میں لفظوں کی جھنکار اور اس کی صوتی قدروقیمت، ترنم اور آہنگ کے قائل شروع سے رہے ہیں۔سیدہ جعفر کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اشارہ کردیا ہے کہ مسعود حسین خان نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے۔سیدہ جعفر گیان چند جین اور بعض دوسرے ادیبوںسے متفق نہیں ہیں۔ البتہ وہ گوپی چند نارنگ کے خیالات سے اتفاق کرتی ہیں کہ’’اس پیرایہ تنقید میں آوازوں کے نظام، الفاظ کے استعمال، اسماء اور افعال کے تناسب اور علم بدیع وبیان کے مختلف اجزا کا مطالعہ کرکے اسلوب کی خصوصیات کے تعین میں مددلی جاتی ہے۔اپنی علمی بنیادوں، معنویت اور انفرادیت کے باوجود اسلوبیات جامع تنقید نہیں ہے۔‘‘
سیدہ جعفر نے اسلوبیاتی تنقید،اس کے ناقدین کے تصورات اور ان تصورات کے معترضین کے اعتراضات پر جس طرح تنقیدی بحث کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم عصر تنقیدکے مختلف رویوں اور رجحانات پر ان کی نظرگہری ہے۔
سیدہ جعفر جدید تنقیدکو قدیم کلاسیکی ادب کی روشنی میں دیکھتی ہیں۔ان کا خیال ہے کہ قدیم کلاسیکی ادب کے اصول وضوابط جدید تنقید کا سرچشمہ ہیں۔گوپی چند نارنگ کی تنقیدی ترجیحات پرتبصرہ کرتے ہوئے سنسکرت قواعد کے موجدپاننی کو سوسیئر اور بودھی مفکرناگرجن کوجو دریدا کا پیشروقرار دیا ہے اورساختیات سے متعلق سوسئیرکے تصورات اور پاننی کے اصول وضوابط ، دریدا کی ردّتشکیل اور ناگرجن کے تصورِ شونیہ جومماثلت دریافت کی ہے اس پر سیدہ جعفرنے اپنے منفرد انداز میںاچھا تبصرہ کیا ہے۔ عربی ادب کے مفکرین ابن قتیبہ، جاحظ اور قدامہ بن جعفر کے نظریۂ لفظ ومعنی اور فارسی کے ماہرین شعریات سمرقندی اور وطواط کے تصورعروض اورصنائع وبدائع پرسیدہ جعفرنے جس طرح روشنی ڈالی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرقی شعریات سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ادب میں زبان کے استعمال اور اظہار کے سلسلے میں سوسئیرنے لانگ سے کیا مراد لیا ہے۔اسی طرح رولاں بارتھ کا یہ نظریہ کہ زبان بولتی ہے انسان نہیں بولتا یا ملارمے کا یہ قول کہ تحریرلکھتی ہے ادیب نہیںوغیرہ سے گوپی چند نارنگ نے کس حد تک اتفاق کیا ہے یا ان سے انحراف کیا ہے وغیرہ مسئلوں پر سیدہ جعفرنے جس طرح سے بحث کی ہے اور اپنی رائے دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مابعد جدید تنقید بھی ان کی نظرسے اوجھل نہیںہے۔
حامدی کاشمیری کا خیال ہے کہ اشعار پر پڑے ہوئے، علامت کے پردے کو ہٹانے کا کام اکتشافی ناقدین کرتے ہیں۔اس سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ شاعر لفظ وپیکر کے علامتی برتاؤ سے تجربات کے جو’رنگ محل‘تعمیر کرتا ہے ان کے ’’طلسمی دروازوں‘‘ کو کھولنا اکتشافی تنقید کا مقصدہے۔
سیدہ جعفرنے علامت کے معنی ومفہوم،اوصاف اور شاعری میں اس کی اہمیت اورحسن کے متعلق مختلف مفکروں کے حوالوں کی روشنی میں جس طرح بحث کی ہے وہ ان کی وسعت مطالعہ اورگہری تنقیدی نظر کا مظہر ہے۔
سیدہ جعفر نے اکتشافی تنقیدکے محرک حامدی کاشمیری کے تصوّرتنقیدپربحث کرتے ہوئے اکثر ان سے اختلاف کیا ہے اور ان کے بعض بیانات کو رد کر دیا ہے۔مثلاً اکتشافی تنقید کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے حامدی کاشمیری نے کہاتھا کہ متن آوازوں، پیکروںاورخاموشیوں سے گہرے طور پر جڑاہوا ہوتا ہے۔ہم آوازوں کے حوالے سے اسلوبیاتی تنقید اور پیکروں کے اعتبار سے ہیئیت پرستوں اور رومانیت پسندوں کے طرزفکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیںلیکن خاموشیاں بین السطور مفہوم اور تاثر ہے جو گفتن اور ناگفتن کے ربط کا مظہر ہے۔حامدی کاشمیری کے ان خیالات کو رد کرتے ہوئے سیدہ جعفر نے یہ سوال قائم کیا ہے کہ تنقید اگر محض نزول پر منحصر ہے تو مطالعے، تجزیے اورشعری تجربے سے آشنائی کیا اہمیت رکھتی ہے؟کیا تنقید کا عمل شعوری نہیں ہوتا؟وغیرہ وغیرہ۔سیدہ جعفر نے حامدی کاشمیری کے ان بیانات کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے جس میں انہوں نے اقبال اور غالب کے دیباچہ میں کہا تھا کہ وہ تخلیق کے اجزا ئے ترکیبی مثلاً پیکر، علامت اور صوتی اثرات سے تشکیل پانے والی ہیئیت میں تجربے کی نمو پذیری کے عمل کی شناخت کرتے ہیں۔سیدہ جعفر نے ان کے تمام بیانات کی روشنی میں یہ کہہ کر کہ حامدی کاشمیری کے بعض بیانات ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں، ان کے تصورتنقید کو رد کردیا ہے ۔سیدہ جعفر نے حامدی کاشمیری کے ان بیانات پر بھی سخت تنقید کی ہے جن میں حامدی کاشمیری نے کہا تھا کہ شاعری نہ زندگی کا ترجمان ہے نہ تنقیدحیات کا۔یہ نہ زندگی اور فطرت کی عکاسی کرتی ہے اور نہ کوئی پیام دیتی ہے نہ زندگی بسر کرنے کا نسخہ۔یہ نہ لوگوں کے انفرادی یا اجتماعی مسائل، دلچسپیوں اورنہ ان کے تعصبات سے ان کی اخلاقی یاذہنی گتھیوں کے بارے میں اطلاعات فراہم کرتی ہے۔ان بیانات پر اعتراض کرتے ہوئے سیدہ جعفر نے لکھا ہے
’’حامدی کاشمیری نے اپنے اس بیان میں ادب کے تہذیبی وسماجی تناظر سے بے تعلقی،اخلاقی اقدار سے بے نیازی اورادب کی زندگی سے عدم وابستگی پرزور دیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ادب میں تہذیبی پس منظراورروح عصرکی اہمیت کے قائل نہیںہیں اور عصری حسیت کو غیر اہم تصوّرکرتے ہیں۔ ‘‘(تفہیم وتجزیہ، ص- 321 )
سیدہ جعفر کے اعتراضات درست ہیں اور ان کی تنقیدسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ثقافتی تنقید کی قائل ہیں۔
سیدہ جعفر کے تنقیدی مضامین میں خاص بات یہ ہے کہ فلسفہ جیسے دقیق مسئلوں کو اکثر زیربحث لایا گیا ہے لیکن ان کی تحریروں کو پڑھ کراکتاہٹ کا احساس نہیں ہوتا کیوں کہ انہوں نے فلسفیانہ تنقید میں شاعرانہ زبان کا استعمال کیا ہے ۔انہوں نے غالب اور اقبال ،فیض ،فراق اور کلاسیکی شعرا کے بعض اشعار، ترکیبیں اور اصطلاحات کو اپنی تحریروں میں جذب کرلیا ہے جس سے ان کی تنقیدی زبان میں وہی روانی ،شیرینی اور کیفیت پیدا ہو گئی ہے جو ان شعرا کے کلام میں پائی جاتی ہے۔
٭٭٭٭