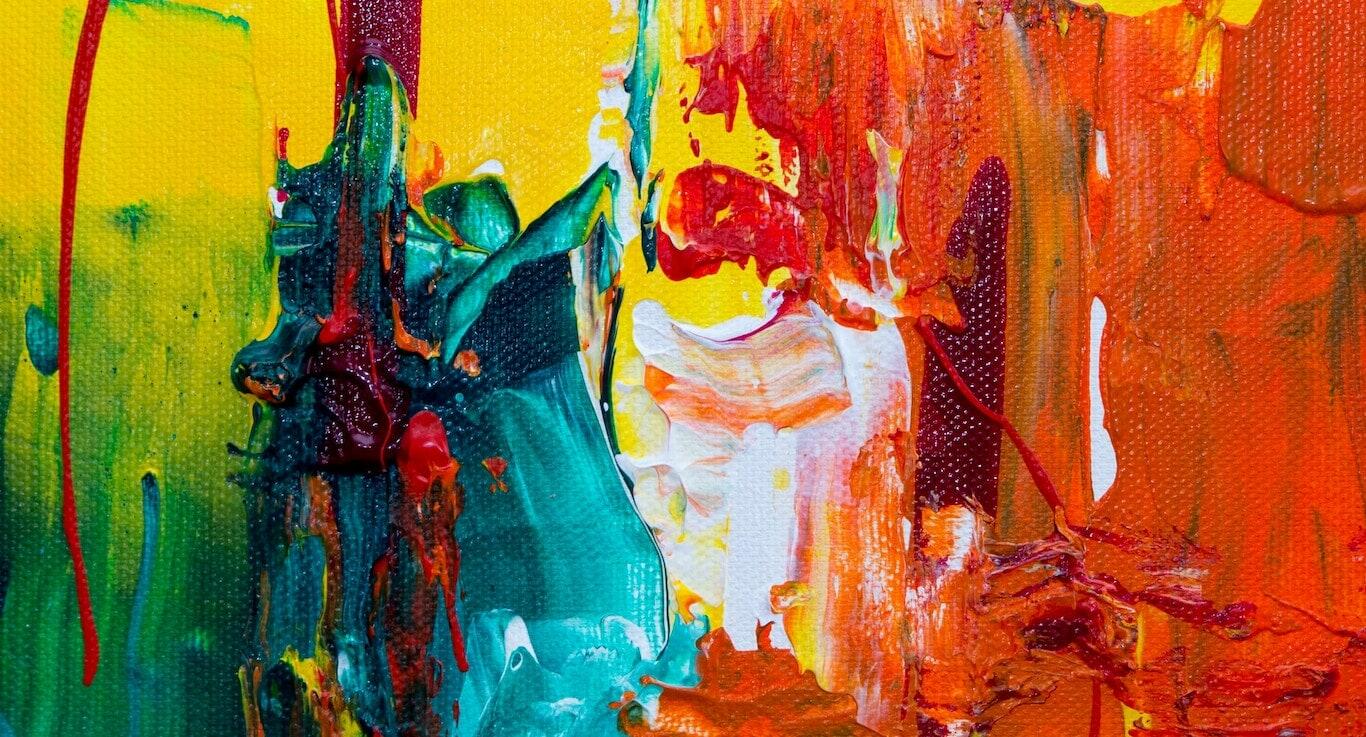شاعری کی اصطلاح میں تضمین وہ فن ہے جس میں تضمین نگار اپنے کسی پسندیدہ شاعر کے کسی پسندیدہ مصرع یا کسی شعر کی داخلی کیفیت اور رنگ و آہنگ کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے اس پر اپنے چند مصرعوں کے اضافے اس حسن و خوبی کے ساتھ کرتا ہے کہ لگائے گئے مصرعے اور اصل شعر یا مصرع شیر و شکر کی طرح ضم ہو کر ایک الگ اکائی بن جاتے ہیں۔ تضمین نگار اس عمل میں اصل شعر یا مصرع کے مفہوم کی توسیع کرتا ہے یا اس کی علامتوں کی نئی توجیہ پیش کرتا ہے جس سے دونوں شاعروں کے تخلیقی عمل کے امتزاج سے ایک نئی فضا اور ایک نئی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ تضمین کا فن بڑا نازک اور لطیف ہے۔ تضمین نگار کو تضمین کرتے وقت کئی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور کئی نازک مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مثلاً وہ سب سے پہلے تفہیمِ شعر کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے کچھ نامکمل پہلوئوں کی تلاش کرتا ہے اور اپنے جذبات یا خیالات سے ہم آہنگ کرکے ان کے مفہوم کو ایک نئی جہت عطا کرتا ہے۔
تضمین کے لیے کسی خاص ہیئت کی قید نہیں ہے۔ مخمس، مثلث، مسدس، ترکیب بند وغیرہ میں تضمین کے فن کی نادر مثالیں مل جاتی ہیں۔ مخمس کے فارم میں دو مصرعے کسی دوسرے شاعر کے ہوتے ہیں جن میں تضمین نگار تین مصرعے اپنی طرف سے اضافہ کرکے پانچ مصرعوں کی ایک الگ اکائی بنا دیتا ہے۔ مثلاً ظفرؔ کا ایک شعر ہے ؎
دیکھتے ہی اے ستم گر، تیری چشمِ نیم باز
کی تھی پوری ہم نے جو تدبیر ، آدھی رہ گئی
غالبؔ نے اس شعر پر اپنے تین مصرعوں کا اضافہ کرکے یوں تضمین کی
غم نے جب گھیرا تو چاہا ہم نے یوں اے دل نواز
مستیِ چشمِ سیہ سے چل کے ہو ویں چارہ ساز
تو صدائے پاسے جاگا تھا جو محوِ خوابِ ناز
’’دیکھتے ہی اے ستمگر، تیری چشمِ نیم باز
کی تھی پوری ہم نے جو تدبیر، آدھی رہ گئی‘‘
اس شعر کی تضمین نے شعر کے ابہام کو دور کر دیا۔ ظفر کے ناتمام مفہوم غالب کوکے مصرعوں نے پورا کر دیا۔ مصرعوں کا دروبست ایسا ہے کہ پانچوں مصرعے ایک ہی شاعر کے کہے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔
مثلث کی شکل میں تضمین نگار اپنے پسندیدہ اشعار پر ایک ایک مصرع لگا کر تین مصرعوں کی ایک اکائی بنا کر پیش کرتا ہے۔ تضمین کی اس شکل کے موجد اور خاتم میر تقی میرؔ ہیں۔ فارسی کے ایک شاعر اہلیؔ کا شعر ہے ؎
امروز یقین شد کہ نداری سراہلی
بیچارہ زلف تو بدل داشث گما نیا
میر نے اس شعر پر ایک مصرع کا اضافہ کر کے یوں تضمین کی
کل تک تو فریبندہ ملاقات تھی پہلی
’’امروز یقین شد کہ ندراری سر اہلی
بیچارہ زلطفِ تو بدل داشت گما نہا‘‘
اہلیؔ کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ آج اہلیؔ کو یقین ہوگیا کہ تجھے اہلیؔ سے کوئی لگائو نہیں ہے بیچارہ اب تک تیرے التفات سے کیسے کیسے گمان رکھتا تھا۔ میرؔ نے اس گمان کی صراحت کردی کہ کل تک تیری ملاقات فریبندہ تھی۔
مسدس کے فارم میں تضمین نگار کسی شاعر کے اشعار پر اپنے چار مصرعوں کا اضافہ کرکے اس کی ایک الگ اکائی بناتا ہے۔ سوداؔ نے ایک مسدس میں فارسی کے تین اشعار پر اردو کے چار مصرعے لگائے ہیں۔ مثلاً
رات آیا وہ صنم سن کے ہمیں زارو نزار
شورِ خلخال میں پہچان کے بولا اک بار
کون ہے ! کہنے لگا دولتِ گیتی اے یار
میں کہا خیر نہ اس بات کو مانوں زنہار
’’دولتِ آنست کہ بے خونِ دل آید بکنار
ورنہ باسعیِ عمل باغِ جناں ایں ہمہ نست‘‘
مسدس کی شکل میں یہ ایک ایسی تضمین ہے جس میں پانچویں اور چھٹے مصرعوں میں قافیہ نہیں ہے یعنی جس شعر کو تضمین کیا گیا ہے وہ مطلع نہیں ہے۔ سو دا نے تضمین کے چاروں مصرعوں کو شعر کے پہلے مصرع کا ہم قافیہ کیا ہے۔ اس طرح مسدس کی روایتی تعریف پر تویہ بند پورا نہیں اترتا لیکن چوںکہ چھ مصرعوں کا ایک بند ہے اس لیے مسدس کے علاوہ کوئی اور نام بھی نہیں دیا جا سکتا ہے۔
اب کچھ ایسی مثالیں پیش کی جاتی ہیں جہاں کسی شاعر کے صرف ایک مصرع کو تضمین کیا گیا ہے۔ ایک مصرع کی تضمین قصیدہ، غزل، طویل نظم یا قطعہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ سوداؔ نے اپنے مشہور قصیدہ، ’’اُٹھ گیا بہمن و دے کا چمنستاں سے عمل‘‘ میں تشبیب کے بہار یہ اشعار میں موسمِ بہار کی مختلف کیفیات بیان کرتے ہوئے اپنی تشبیب کو عرفیؔ کے اس مصرع پر ختم کیا ہے
تاکجاشرح کروں میں کہ بقول عرفیؔ
’’اخگراز فیضِ ہوا سبز شود درمنقل‘‘
سودا نے اپنی ایک غزل کے مقطع میں خواجہ میر درد کے مصرع کو تضمین کیا ہے
میں کیا کہوں کہ کون ہوں سودا بقول درد
’’جو کچھ کہ ہوں سوہوں غرض آفت رسیدہ ہوں‘‘
سودانے ہی فارسی کے ایک ضرب المثل مصرع کو بڑی بے ساختگی کے ساتھ ایک قطعہ میں تضمین کیا ہے
تیرے جویا ہیں اس چمن میں ہم
ڈھونڈے ہے گل کو عندلیب اے دوست
تو برامان مت مضائقہ کیا
’’فکرِ ہر کس بقدرِ ہمت اوست‘‘
مخمس کی شکل میں عہد میرؔ سے دور حاضر تک کے شعراکے کلام میں غزل کے اشعار کی تضمین کے نمونے بے شمار ملتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل کے اشعار کی رمزیت اپنے مفہوم کی توضیح کے لیے کم سے کم مزیدتین مصرعوں کی وسعت چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تضمین کی اس شکل کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ مخمس کو ہی تضمین سمجھا جاتا رہا اور مخمس کو ہی ذہن میں رکھ کر اکثر و بیشتر حضرات نے اس کے فن پر گفتگو کی ۔ بیسویں صدی میں تضمین اپنی روایتی طلسم سے آزاد ہوگئی۔
جب قوم کا مجموعی شعور نئے ماحول، نئے خیالات اور مغربی اثرات سے متاثر ہوا اور تمام اصناف میں سب سے زیادہ ہر دلعزیز صنف نظم قرار پائی تو تضمین بھی اب بجائے دوسری اصناف کے نظم میں ہی زیادہ کہی جانے لگی۔ نظم کی ہیئت میں تضمین کتنے کا عمل شبلی، اقبال اور جوش جیسے ممتاز اور جلیل القدر شعرا ہی کے یہاں ہی نہیں بلکہ اس پوری نسل کے قابلِ ذکر تمام شاعروں کے یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔
شبلی اور اقبال نے اپنی قومی اور اصلاحی نظموں میں فارسی کے مشہور اشعار تضمین کرکے نہ صرف نظموں کی تاثیر کو بڑھایا بلکہ تضمین کے قدیم فن کو وسعت بھی دی اور یہ ثابت کردیا کہ تضمین کافن اثر آفرینی اور ایجاد معانی کے کیسے کیسے امکانات کا حامل ہے۔ اب تضمین کافن خمسہ کی روایتی طلسم سے آزاد ہو کر اپنی تخلیقی صلاحیت کو بروئے کار لانے کے نئے نئے اسالیب تلاش کرنے لگا۔
اقبال نے فارسی کے برگزیدہ شعرا کے اعلی ترین اشعار پر تضمین کی ہے اقبال کے اس شاعرانہ عمل سے تضمین کے فن کی اہمیت پر مُہرِ تصدیق ثبت ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ اقبال کسی مشہور اور بلند پایہ شاعر کی شہرت کے سہارے اپنی ناموری نہیں چاہتے۔ اقبال روایت پرست شاعروں کی طرح قافیہ پیمائی کے قائل نہیں ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ان کی شاعری کا تصوًر بھی اردو شاعری کی روایت سے مختلف ہے۔ وہ شاعروں کو دیدۂ بینائے قوم سمجھتے ہیں اور قوم کے درد میں آنسو بہانے کو شاعری کا مقًدس فریضہ قرار دیتے ہیں۔ شعری روایت کو تو سیع دے کر قدیم اصناف کو جدید تر خیالات کے اظہار کا وسیلہ بنا دینا اقبال کا کارنامہ ہے۔ انہوں نے جس طر ح پرانی علامتوں کو نئے معانی دیے اسی طرح بعض قدیم اسالیب کو بھی نئی معنویت کے ابلاغ کا ذریعہ بنایا۔ تضمین میں کسی رمزیت کو نئی توجیہہ اور نئی تعبیر کا حامل بنا دینا کمالِ فن سمجھا گیا ہے۔ اقبال نے اپنی نظموں میں اس فن کا جیسا جادو جگایا ہے اس کی نظیر اردو شاعری کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ فارسی اساتذہ کے اشعار کو اپنی نظم کے اشعار سے اس طرح پیوست کیا ہے کہ اگر اس نظم سے وہ شعر ہٹا دیا جائے تو نظم ناتمام معلوم ہوتی ہے۔ تضمین کا یہ انداز شبلی نے اردو نظم کو دیا جس سے تضمین کے امکانات کی وسعت نمایاں ہوئی۔ اقبال ان تمام امکانات کو بروئے کار لائے، اقبال کی بدولت تضمین کے فن کو نئی زندگی ملی، اس کی معنویت اور اہمیت مسلّم ہوئی۔ اقبال کی تضمین نگاری پر سید حامد نے لکھا ہے
’’اقبال نے تضمین کے کردار اور اس کے روپ کو بدل ڈالا۔ وہ تضمین کو بالعموم کسی سلسلۂ خیال یا کسی زنجیرِ احساسات پر مہرِ تصدیق ثبت کرنے کے لیے کام میں لایا ہے جیسے انگریزی سانیٹ میں آخری دو مصرعے اور اردو رباعی میں آخری مصرع، جذبے یا خیال کے سلسلہ کو آن بان کے ساتھ پایۂ اتمام تک پہنچاتا ہے۔ لیکن نہ سانیٹ کے آخری دو مصرعوں میں وہ گنبدِ آسا حسنِ اتمام، نہ رباعی کے آخری مصرع میں وہ فکری و سعت اور نہ ان دونوں میں سے کسی میں وہ حُسن اور حیرت ملتی ہے جو اقبال کی تضمینوں کا طرًۂ امتیاز ہے۔ اقبال کے یہاں تضمین کا احسان دو طرفہ ہے۔ نظم کو تضمین سے چار چاند لگ جاتے ہیں اور جس شعر پر تضمین کی گئی ہے اس کو اقبال حسنِ تضمین سے وہ معنویت دے دیتا ہے جو اصلاً اس میں تھی نہیں۔ ایک ایسی صنف سخن کو جسے کہنہ مشقی اور استادانہ مہارت راس آئی تھی اور جس میں مصرع پر مصرعے اور مضمون پر مضمون چسپاں کرنے کی مشق کی جاتی، جس کے مختلف (پنچ مصرعی) بند مضمون کے تسلسل سے اسی طرح محروم تھے جیسے بالعموم غزل کے اشعار، ایسی صنف سخن کو اقبال نے فکری تسلسل کا سرمایہ دار بنا دیا۔‘‘
اب اقبال کی ان نظموں کا مختصر تنقیدی جائزہ پیش کیا جاتا ہے جن کی بنیاد کسی فارسی شعر پر رکھی گئی ہے۔
اقبال کی نظم ’’تصویرِ درد‘‘ ترکیب بند کی شکل میں ہے۔ اس نظم کے ہر بند میں کچھ شعر ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہر بند کے آخر میں ایک شعر مطلع کی شکل میں ہوتا ہے جس کے قافیے اس بند کے قافیوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ تصویر ِدرد میں اقبال نے اپنے وطن اور اہلِ وطن کے مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پوری نظم ایک دردمند محبًِ وطن انسان کے جذبات کی آئینہ دار ہے۔ نظم کے آخری بند میں اقبال اپنی داستانِ درد کو ختم کرنے سے پہلے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ داستانِ درد کا طول خا موشی اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ نظم کا خاتمہ فارسی کے اس شعر کی تضمین پر ہوتا ہے ؎
نمی گردید کو تہ رشتۂ معنی رہا کردم
حکایت بود بے پایاں، بخاموشی ادا کردم
فارسی کے اس شعر سے اقبال نے نظم کی آرائش اور تاثیر کی افزائش دونوں کام لیاہے۔ اس انداز کی تضمین میں پیوند کاری قافیہ کی ایسی پابند نہیں ہوتی جیسی روایتی تخمیس میں ہوتی ہے۔ ’’تصویرِ درد‘‘ اقبال کی مشہور اور مقبولِ عام نظموں میں شمار ہوتی ہے۔ اس قبولِ عام نظم کے بر جستہ اور موثر خاتمہ کا سبب ایک برجستہ اور بر محل شعر کی کا میاب تضمین ہے۔ اس خوشگوار تجربے کے بعد اقبال نے اپنی متعدد نظموں کو تضمین کے فن سے آراستہ کیا اور ہر نظم میں اقبال کی تضمین نکھرتی چلی گئی۔
’’نالۂ فراق‘‘ (آرنلڈ کی یاد میں)‘‘ مسدس کی شکل میں ہے۔ اس ہیئت میں تضمین کے اوّلین نمونے سودا کے کلام میں ملتے ہیں۔ اس میں جس شعر پر تضمین کی جاتی ہے وہ بیت کے طور پر مسدس کے بند کی تکمیل کرتا ہے۔ کامیاب تضمین میں مسدس کے بند کا چوتھا مصرع تضمین کیے جانے والے شعر سے اسی طرح مربوط ہوتا ہے جیسے تخمیس میں تیسرا مصرع چوتھے اور پانچویں سے ربط رکھتا ہے۔ مسدس کا چوتھا مصرع اتنا ہی پرزور اور بر جستہ ہونا چاہیے جیسے رباعی کا چوتھا مصرع۔ اقبال نے مسدس میں تضمین کی اس تکنیک کو بڑی کا میابی کے ساتھ برتا ہے۔
پروفیسر آرنلڈ کی جدائی اقبال کے لیے ناقابلِ برداشت تھی۔ وہ آرنلڈ سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے تھے۔ آرنلڈ کا ہندوستان سے واپس چلا جانا اقبال کے لیے ایک سانحہ سے کم نہیں تھا۔پہلے بند کے ابتدائی تین مصرعوں میں اپنے دردو کرب کا اظہار کرنے کے بعد چوتھے مصرع میں یہ کہہ کر ’’ظلمتِ شب سے ضیائے روز و فرقت کم نہیں‘‘ فارسی کے اس شعر کی تمثیل کو اپنے احساسات کا ترجمان بنا دیا ؎
تاز آغوشِ و داعش داغِ حیرت چیدہ است
ہمچو شمعِ کشتہ درچشم نگو خوابیدہ است
اس بند میں غم انگیز کیفیت کو بے تکلفی کے ساتھ شاعرانہ آب و رنگ دے دینا اقبال کا کمال ہے۔ تضمین کے بغیر اس بند میں یہ زور واثر پیدا کرنا ناممکن تھا۔ ضیائے روز فرقت کو ظلمتِ شب سے تعبیر کرنے کی کیسی عمدہ توجیہہ فارسی کے اس شعر سے ہوئی ہے کہ میری نگاہ بجھی ہوئی شمع کی طرح سوگئی ہے۔یعنی آنکھ کی بینائی جاتی رہی ہے۔
جابسا مغرب میں آخر اے مکاں تیرا مکیں
آہ! مشرق کی پسند آئی نہ اس کو سرزمیں
آگیا آج اس صداقت کا مرے دل کو یقین
ظلمتِ شب سے ضیائے روز فرقت کم نہیں
’’تاز آغوشِ و داعش داغ حیرت چیدہ است
ہمچو شمعِ کشتہ درچشم نگو خوابیدہ است‘‘
یہی صورت تیسرے اور چوتھے بند میں بھی ہے۔ تیسرے بند میں اپنی ناتمامی کے احساس کو بیان کرنے کے بعد یہ کہنا کہ ابرِ رحمت میرے باغ سے اپنا دامن اٹھا کر میری اُمید کی کلیوں کو تھوڑی سی شادابی دے کر چلا گیا۔ چوتھے بند میں اس شعر کی علامتوں کو اپنے مصرعوں کی مدد سے نیا مفہوم دے کر پورے بند کے اثر کے دائرہ کو بڑھا دیا ہے۔
اقبال کی ایک نظم کا عنوان ہے ’’تضمین بر شعر انیسی شاملو‘‘۔ انیسی ساملو کا یہ شعر ؎
وفا آموختی ازما، بکارِ دیگراں کر دی
ربو دی گوہر ے اَزما، نثارِ دیگر اں کردی
(یعنی تونے ہم سے وفا سیکھی اور دوسروں پر صرف کی، موتی ہم سے اڑایا اور دوسروں پر لٹایا)
جس پر تضمین کر کے اقبال نے اپنی نظم کی عمارت تعمیر کی ہے وہ غزل کا شعر ہے اور تغزّل کی چاشنی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اقبال نے اس شعر پر اپنی ناصحانہ نظم کو ختم کیا ہے۔ فارسی غزل کے شعر سے اردو نظم کا کیف واثر دوبالا ہو گیا ہے۔ اقبال نظم میں ڈرامائی فضا پیدا کرنے کے لئے اکثر مکالماتی انداز اختیار کرتے ہیں اس نظم میں بھی زور واثر اسی انداز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ مغربی تعلیم ان کو دین سے بیگانہ بنا رہی ہے۔
ہوئی ہے تربیت آغوشِ بیت اللہ میں تیری
دلِ شوریدہ ہے لیکن صنم خانہ کا سودائی
’’وفا آموختی ازما بہ کار دیگراں کر دی
ربودی گوہرے ازما، نثارِ دیگراں کر دی‘‘
’’نصیحت‘‘ ایک طنزیہ اصلاحی نظم ہے۔ اس کی بنیاد حافظ کے اس شعر پر رکھی گئی ہے۔
عاقبت منزل ماوادی خاموشاں است
حالیہ غلغلہ در گنبدِ افلاک انداز
حافظ کے اس شعر کی ردیف ’’انداز‘‘ کو قافیہ بنا کر نظم کے اشعار سے حافظ کے شعر کو ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ نظم قطعہ کی صورت میں ہے اور حافظ کا شعر نگینہ کی طرح آخر میں جڑ دیا گیا ہے جس سے نظم کے حسن کو چار چاند لگ گئے ہیں۔ اس نظم میں طنز کا ہدف تو اقبال نے اپنی ذلًت کو بنایا ہے لیکن در حقیقت یہ طنز اس عہد کے لیڈروں پر ہے جو اپنی ریاکاری سے پوری قوم کو گمراہ کر رہے تھے۔
’’خطاب بہ جوانان اسلام‘‘ اقبال کی ایک مشہور نظم ہے۔ یہ نظم غنی کا شمیری کی مشہور غزل کے مقطع پر تضمین ہے ۔
غنی روزِ سیاہِ پیر کنعاں راتماشا کن
کہ نور دیدہ اش روشن کند چشمِ زلیخارا
یہ نظم بھی قطعہ کی صورت میں ہے اور اس کے اشعار غنی کا شمیری کے شعر کے دوسرے مصرع کے ہم قافیہ ہیں۔ غنی کے شعر کی رمزیت کی اثر آفرینی کے امکانات کو بروئے کار لاکر پیر کنعاں اور زلیخا کی علامتوں کو نیا مفہوم دے دیا ہے۔ یہ نظم صرف ایک تضمین ہی نہیں ہے، فکری اور فنّی اعتبار سے ایک تخلیقی کارنامہ بھی ہے۔ اقبال نے اس نظم میں مسلم نوجوانوں کو ان کے شاندار ماضی کی یاد دلائی ہے۔ معنی خیز تر کیبوں کی مدد سے نظم کی ابتدا میں اسلامی شعار اور کردار کی تصویر پیش کی ہے۔ چوتھے شعر میں حافظ کی مشہور غزل کے بہت ہی مشہور مصرع کو اس کا ریگری کے ساتھ تضمین کیا ہے کہ غزل کی معروف علامتوں کا مفہوم یکسر بدل کر رہ گیا۔ الفقر فخری کی دلنشیں تفسیر غزل کی زبان میں پیش کر دی۔ اصلاحی نظم میں ایسی شعریت پیدا کر دینا اقبال کا کمال ہے۔ بحر کی نغمگی سے اشعار گنگناتے ہیں۔
یورپ میں اقبال کو اپنے اسلاف کی وہ کتابیں جب نظر آئیں جن سے ظلمتِ یورپ نے نورِ دانش حاصل کیا تو ان کا دل تڑپ اُٹھا ۔ اس درد و کرب کی ترجمانی غنی کے شعر کی مدد سے جیسی بھر پور ہوئی ہے کسی اور پیرایۂ اظہار سے ممکن ہی نہ تھی۔ نظم پیشِ خدمت ہے۔
کبھی اے نوجواں مسلم ! تدبرّ بھی کیا تونے ؟
وہ کیا گردوں تھا، تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا؟
تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوشِ محبت میں
کچل ڈالا تھا جس نے پائوں میں تاجِ سر دارا
تمدن آفرین، خلاقِ آئینِ جہاں داری
وہ صحرائے عرب، یعنی شتر بانوں کا گہوارا
سماں اَلفقر فخری کا ر ہا شان امارت میں
’’بآب و رنگ وخال وخط چہ حاجت روئے زیبارا‘‘
گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے
کہ منعم کو گدا کے ڈرسے بخشش کا نہ تھا یارا
غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحر انشیں کیا تھے
جہاں گیرو جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا
گر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں
مگر تیرے تخیّل سے فزوں تر ہے وہ نظّارا
تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی
کہ تو گفتار، وہ کردار، توثابت، وہ سیارا
گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میرا ث پائی تھی
ثریّا سے زمیں پر آسماں سے ہمکودے مارا
حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ اک عارضی شے تھی
نہیں دنیا کے آئینِ مسلم سے کوئی چارا
مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی
جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا
’’غنی روزِ سیاہِ پیرِ کنعاں راتما شاکن
کہ نورِ دیدہ اش روشن کند چشمِ زلیخارا‘‘
نظم ’’تعلیم اور اس کے نتائج‘‘ میں اقبال نے ملاّ عرشی کے شعر کو تضمین کیا ہے۔ تین شعروں کے اس قطعہ میں اقبال نے مغربی تعلیم کی اہمیت کا اعتراف بھی کیا ہے اور اس تعلیم کے نتیجہ میں جو بے دینی کا رجحان پیدا ہوا اس سے بیزاری کا اظہار بھی ۔ملاعرشی کے شعر نے اقبال کے اس تاثر کو اور بڑھا دیا ہے۔ فارسی کے شعر کا یہ مفہوم اقبال کے تاثرات سے کیسا مربوط ہے کہ اب ایک اور بیج لے کر پھر سے بو دیں۔ اس سے پہلے جو کچھ بویا تھا اسے تو شرم کے مارے ہم کاٹ نہیں سکے۔
خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر
لبِ خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ
ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم
کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ
گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما
لے کے آئی ہے مگر تیشۂ فرہاد بھی ساتھ
’’تخمِ دیگر بکف آریم وبکاریم زنَو
کا نچہ کشتیم زخجلت نتواں کرد درو‘‘
نظم ’’قربِ سلطان‘‘ خواجہ حافط شیرازی کے شعر پر تضمین ہے۔ اس تضمین میں ایک نمایاں بات یہ ہے کہ نظم کے پانچویں، چھٹے اور ساتویں شعر میں حافظ کی اسی غزل کا ایک ایک مصرع تضمین ہوا ہے۔ اس طرح تضمین کا بالکل ایک نیا نمونہ اقبال نے اردو شاعری کو دیا۔ پیش ہے اس نظم کے پانچویں، چھٹے اور ساتویں شعر جن میں حافظ کے غزل کا ایک ایک مصرع تضمین کیا گیا ہے
پرانے طرِز عمل میں ہزار مشکل ہے
نئے اصول سے خالی ہے فکر کی آغوش
مزا تو یہ ہے کہ یوں زیر آسماں رہیے
’’ہزار گونہ سخن در دہان و لب خاموش‘‘
یہی اصول ہے سرمایۂ سکونِ حیات
’’گدائے گوشہ نشینی تو حافظا مخروش‘‘
مگر خروش پہ مائل ہے تو، تو بسم اللہ
’’بگیر بادۂ صافی، ببانگ چنگ بنوش‘‘
حافظ کے شعر پر اقبال کی نظم کا اختتام اس طرح ہوا ہے
پیامِ مرشدِ شیراز بھی مگر سن لے
کہ ہے یہ سرِّ نہاں خانۂ ضمیرِ سروش
’’محلِ نورِ تجلّی است رائے انورِ شاہ
چوقرب روطلبی درصفائے نیّت کوش‘‘
’’تضمین بر شعر ابو طالب کلیم‘‘۔ علامہ اقبال نے اس قطعہ کے اشعار کو ابو طالب کلیم کے شعر کا ہم قافیہ رکھا ہے۔ اس قطعہ کا موضوع بھی وہی ہے جو اس دور کی شاعری کا بنیادی موضوع ہے۔ یعنی مغرب زدہ مسلمانوں کو اس کے دین کی طرف واپس لانا۔ اقبال نے اپنے عہد کے تعلیم یافتہ مسلمانوں کو اس کی زندگی اور اس کے اسلاف کی زندگی کا فرق بتا کر یہ پیغام دیا ہے کہ اسے اپنے آبائی عقائد اور شعار کی طرف واپس آنا چاہیے اس کے تاثر کو ابو طالب کلیم کے شعر کی اس تمثیل نے کہ ’’شعلہ جہاں سے اٹھتا ہے وہیں بیٹھتا ہے‘‘ بے کراں بنا دیا ہے
غافل ! اپنے آشیاں کو آکے پھر آباد کر
نغمہ زن ہے طورِ معنی پر کلیمِ نکتہ بیں
’’سرکشی باہر کہ کردی رام اوباید شدن
شعلہ ساں ازہر کجا بر خاستی آنجانشیں‘‘
’’شبلی وحالی‘‘،یہ نظم شبلی و حالی دونوں کا مرثیہ ہے۔ ان کے قومی درد کو بڑی ندرتِ ادا کے ساتھ اس نظم میں نمایاں کیا گیا ہے۔ اقبال اپنی نظموں میں مکالماتی انداز سے ایک ڈرامائی فضا پیدا کر دیتے ہیں۔ اس نظم میں بھی اقبال نے جب مسلمانوں سے پوچھا کہ تیرا ماضی تو بہت شاندار تھا اب تیرے باغ میں خزاں کیوں آگئی۔ چمن کے دیر ینہ راز داروں سے اس کا سبب تو پوچھو۔ اس نے کہا کہ چمن کے جو راز دار تھے وہ تو خاموش ہیں۔ ابھی شبلی کے ماتم سے فرصت نہیں ملی تھی کہ حالی بھی فردوس کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس گفتگو کے پس منظر فارسی شعر کی پرانی علامتوں کی جدید معنویت نمایاں ہوتی ہے کہ اب یہ ہوش کسے ہے کہ باغباں سے پوچھے کہ بلبل نے کیا کہا، گل نے کیا سنا اور صبا نے کیا کیا ۔
شبلی کو رو رہے تھے ابھی ا ہل ِ گلستاں
حالی بھی ہو گیا سوئے فردوس رہ نورد
اکنوں کرا د ماغ کہ پرسد زباغباں
بلبل چہ گفت و گل چہ شنیدو صباچہ کرد‘‘
نظم ’’ارتقا‘‘ میں فارسی کے جس شعر کو تضمین کیا گیا ہے اس کے حسن تمثیل نے اقبال کے فلسفہ ارتقا کو اپنی شعر یت اور حسنِ ادا سے دلنشیں بنا دیا ہے۔ نظم کا آخری شعر ہے ۔
اسی کشا کشِ پیہم سے زندہ ہیں اقوام
یہی ہے راز تب وتابِ ملًتِ عربی
اس شعر کو تضمین کی صورت میں مربوط کیا ہے فارسی کے اس شعر سے
مغاں کہ دانۂ انگور آب می سازند
ستارہ می شکنند آفتاب ہی ساززا
(انگور کے دانہ سے شراب بنانے والے ستارہ کو توڑ کر آفتاب بنا رہے ہیں) حسنِ تضمین نے اقبال کے پیغام کے لطف و اثر کو دوبالا کر دیا ہے۔
’’تہذیبِ حاضر‘‘ (تضمین بر شعر فیضی)۔ اس نظم میں اقبال نے فیضی کے ایک شعر کی تضمین کی ہے۔ اقبال نے اس شعر پر تضمین کے جو اشعار کہے ہیں ان میں تہذیب حاضر کی چمک دمک سے متاثر ہونے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ نئی تہذیب کی لذتیں رقابت، خود فروشی، ناشکیبائی ، ہوس ناکی ہیں جو تمہیں تمہارے دین اور دین کے شعار س سے بیگانہ بنا رہی ہیں۔ تم اپنی تہذیب سے اپنی شخصیت کو آراستہ کرو۔ فارسی شعر کی پرانی علامتیں تضمین کے اشعار سے مربوط ہو کر نئی فضا اور نئی جہت دے ر ہی ہیں۔
فروغِ شمعِ نو سے بزم مسلم جگمگا اٹھی
مگر کہتی ہے پروانوں سے میری کہنہ ادرا کی
’’تو اے پروانہ! ایں گرمی زشمعِ محفلے داری
چومن در آتشِ خود سوز اگر سوزِ دلے داری‘‘
(اے پروانے تونے یہ گرمی شمعِ محفل سے حاصل کی ہے ۔ اگر تجھے جلنا ہے تو میری طرح اپنی آگ میں جل)
نظمِ ’’ عرفی‘‘ میں اقبال نے عرفی کے جس شعر پر تضمین کی بنیاد استوار کی ہے اس کے پہلے مصرع سے نظم کا قافیہ بھی حاصل کیا ہے۔ نظم عرفی کے تخیل کی بلندی کے اعتراف سے شروع ہوتی ہے ۔ پھر اقبال اپنے مخصوص ڈرامائی انداز میں عرفی کی تربت سے شکا یت کرتے ہیں کہ مزاجِ اہلِ عالم میں ایسا تغیر آگیا ہے کہ سب غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور سامانِ بے تابی کہیں نہیں ملتا۔ اس شکا یت کے جواب میں عرفی کی تربت سے یہ آواز آتی ہے کہ
نوارا تلخ تری زن چوذوق نغمہ کم یابی
حدی راتیز ترمی خواں چو محمل راگراں بینی
(جب نغمہ کا ذوق کم ہو جائے تو آواز اور اُونچی کردو، محمل اگر بھاری ہو تو حدی کی لے کو تیز کر دو)
’’ایک خط کے جواب میں‘‘حافظ کے شعر کی یہ تضمین منظوم جواب ہے اس خط کا جس میں کسی کرم فرمانے اقبال کو حکام سے ربط و ضبط بڑھا نے کا مشورہ دیا تھا۔ اقبال نے ان کو یہ جواب دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔میرے لیے یہی کافی ہے کہ میری شاعری سے دلوں کو شادابی مل رہی ہے۔ بادشاہوں کے دربار سے وابستگی وہ لوگ چاہتے ہیں جو مردہ دل ہیں۔ حافظ شیراز نے مجھ پر یہ راز منکشف کر دیا ہے کہ اگر خضرکی ہم نشینی چاہیے ہو تو آبِ حیات کی طرح سکندر کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو
ہوائے بزم سلاطین ، دلیلِ مردہ دلی
کیا ہے حافظِ رنگیں نوانے رازیہ فاش
’’گرت ہوا ست کہ باخضر ہم نشیں باشی
نہاں زچشمِ سکندر چوں آبِ حیواں باش‘‘
’’کفر و اسلام ‘‘ (تضمین برشعررضی دانش) ۔ رضی دانش کے شعر میں حاضر اور غائب کے لیے دو دلنشیں تمشیلیں ہیں۔ اقبال نے اپنے معروف مکالماتی انداز میں ان تمشیلوں کی مدد سے کفرو اسلام کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ اقبال حضرت موسیٰ ؑسے پوچھتے ہیں کہ نمرود کا شعلہ اب تک شعلہ ریز ہے مگر تیرا سوز کہن آنکھوں سے پنہاں ہے۔ حضرتِ موسیٰ جواب دیتے ہیں کہ تو غائب کو چھوڑ کر حاضر کا شیدائی نہ بن۔ اس موازنے کا خاتمہ اس شعر پر ہوتا ہے
’’شمع خود را می گداز درمیانِ انجمن
نورِ ماچوں آتشِ سنگ از نظر پنہاں خوش است‘‘
(شمع محفل میں جل رہی ہے مگر ہمارا نور نظروں سے اس طرح پوشیدہ ہے جیسے پتھر میں آگ چھپی ہوئی رہتی ہے۔ یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔)
’’مسلمان اور تعلیمِ جدید‘‘ (تضمین برشعر قمی)۔ اس تضمین میں اقبال نے مسلمانوں کی تعلیمی پستی کو اپنی نظم کا موضوع بنا یا ہے اور’ ملک قمی‘ کے اس شعر پر اپنی نظمِ کو ختم کیا ہے
رفتم کہ خار ازپا کشم، محمل نہاں شداز نظر
یک لحظہ غافل کشتم و صد سالہ راہم دور شد
(میں اپنے پیر کا کانٹا نکالنے میں رہا اور محمل میری نظر سے چھپ گیا۔ ذرا سی غفلت سے سیکڑوں سال کا فاصلہ بڑھ گیا۔)
تضمین کے کمال نے فارسی شعر کی علامتوں کی معنویت میں جو نیا پن بخشا ہے،وہ اقبال کے حسنِ انتخاب ، تازہ کاری اور قدرتِ بیان کا آئینہ دار ہے۔
’’تضمین بر شعر صائب ‘‘ یہ نظم قوم کی بے حسی کا مرثیہ ہے۔ اس نظم میں تضمین کے لیے جس شعر کا انتخاب کیا گیا ہے وہ صائب کے بہترین اشعار میں سے ایک ہے۔ تغزل سے بھر پور اس شعر کی تضمین میں جن اشعار کا اضافہ کیا گیا ہے وہ قوم کے بے حسی پر طنز کے نشتر ہیں مگر آب و رنگِ شاعری میں۔ اقبال کو یہ شکوہ ہے کہ قوم بیداری کا پیغام سننا نہیں چاہتی۔ قوم کے بزرگ بھی بے حس ہیں اور نوجوان بھی جب یہ صورت ہو اور ضبطِ نوا بھی ممکن نہ ہو تو اس باغ سے اڑ کر کسی صحرا میں جا بیٹھنا بہتر ہے۔ صائب کے اس شعر نے نظم کا لطف و اثر اور بڑھا دیا۔
نہیں ضبطِ نوا ممکن تو اڑ جا اس گلستاں سے
کہ اس محفل سے خوشتر ہے کسی صحرا کی تنہائی
’’ہماں بہتر کہ لیلیٰ در بیا باں جلوہ گربا شد
ندارد تنگنائے شہر تابِ حسنِ صحرائی‘‘
(یہی بہتر ہے کہ لیلیٰ بیاباں میں رہے۔ شہر کی تنگ فضا حسن صحرائی کی تاب نہیں لا سکتی۔)
’’فردوس میں ایک مکالمہ۔‘‘ یہ نظم سعدی کے ایک حکیمانہ شعر پر تضمین ہے۔ اپنے مکالماتی اسلوب میں اقبال نے ایک اور جدّت کی ہے۔ وہ یہ کہ حالی اور سعدی کے درمیان مکالمہ ہے۔ دوسری پرلطف بات یہ کہ اقبال نے حالی کو اپنا خراج عقیدت سعدی کی زبان سے فارسی شعر میں پیش کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری نظم کے موتی کے نور نے آسمان کو جگمگا دیا اور اس کے سامنے چاند تاروں کی روشنی ماند پڑ گئی ہے۔ اس خراج عقیدت کے بعد سعدی نے حالی سے ہندو ستان کے مسلمان کی کیفیت پوچھی تو حالی نے جواب دیا کہ نئی تعلیم کے عام ہونے کے بعد مسلمانوں کے عقیدے میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ مگر یہ بات شہ یثربؐ کے حضور میں نہ کہنا ورنہ ہند کے مسلمان مجھے چغل خور سمجھیں گے۔ تضمین کا کمال یہ ہے کہ حالی کے اس کفتگو کے بعد اقبال سعدی کے اس شعر پر اپنی نظم کو ختم کرتے ہیں
یہ ذکرِ حضورِشہ یثربؐ میں نہ کرنا
سمجھیں نہ کہیں ہند کے مسلم مجھے غمّاز
’’خرما نتواں یافت ازاں خار کہ کشتیم
دیبا نتواں ازاں پشم کہ رشتیم‘‘
(ہم نے جو کانٹے بو ئے ہیں ان سے ہمیں کھجوریں نہیں مل سکتی ہیں۔ جو اُون ہم نے کاتا ہے اس سے ریشمی کپڑا نہیں بن سکتے)
’’مذہب‘‘ (تضمین برشعر میرزا بیدل)۔ روایتی تضمین میں خمسہ کا تیسرا مصرع اس شعر سے مربوط ہوتا ہے جس پر تضمین کی جاتی ہے۔ اقبال کی نظموں میں تضمین کی حیثیت محض آرائشِ سخن کی نہیں ہے۔ وہ تضمین کے فن کو اظہار کا ایک موثر و سیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان کی نظموں میں تمام اشعار اس شعر سے معنوی ربط رکھتے ہیں جس پر تضمین کی گئی ہے۔ اس نظم میں وہ اس حقیقت کو آشکارکرتے ہیں کہ مغربی تعلیم کے دور میں عقائد کا شیشہ پاش پاش ہو رہا ہے مگر زندگی کا فلسفہ یہ بتاتا ہے کہ
باہر کمال اند کے آشفتگی خوش است
ہر چند عقلِ کُل شدۂ بے جنوں مباش
(ہر کمال کے ساتھ تھوڑی سی دیوانگی بھی ضروری ہے۔ تو کتنا ہی باعقل ہو جائے جنون سے بیگانہ نہ ہو)
بیدلؔ کے شعر میں جنون کو مذہب کا استعارہ قرار دے کر اقبال نے شعر کو نیا مفہوم دے دیا جو ان کی نظم سے پوری طرح ہم آہنگ ہو گیا ہے
مذہب ہے جس کا نام وہ ہے اک جنونِ خام
ہے جس سے آدمی کے تخیل کو انتعاش
کہتا مگر ہے فلسفۂ زندگی کچھ اور
مجھ پر کیا یہ مرشدِ کامل نے راز فاش
’’باہر کمال اندکے آشفتگی خوش است
ہر چند عقلِ کل شدۂ بے جنوں مباش‘‘
’’دنیائے اسلام‘‘۔ اس نظم کے پہلے بند میں اقبال نے ترکی، عرب اور ایران کی تباہی کی داستان سنانے کے بعد کہ انگریز کی سیاست نے ان ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ خضر کی زبان سے یہ کہلو ایا ہے کہ تو اس بر بادی پر اس لیے پر یشان ہے کہ تو رازِ مشیت سے آگاہ نہیں ہے۔ اقبال نظم کے خاتمہ پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر تخریب میں تعمیر چھپی ہوئی ہے۔ لیکن اس بات کو اپنی زبان سے نہیں کہا، مولانا روم کی زبان سے کہلوایا ہے۔ مولانا روم کی مثنوی کا جوشعر یہاں تضمین کیا گیا ہے اس کے وزن کو اپنی نظم کے وزن کے مطابق کرنے کے لیے اقبال نے پہلے مصرع میں ’’گفت رومی‘‘ اور دوسرے مصرع میں ’’می ندانی‘‘ کے ٹکڑوں کا اضافہ کیا ہے۔ یہ ندرت بھی اقبال کا ہی ذہنِ رسا پیدا کر سکتا تھا
ہو گیا مانندِ آب ارزاں مسلماں کا لہو
مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز
’’گفت رومی ہر بنائے کہنہ کا باداں کنند
می ندانی اوّل آں بنیاد راویراں کنند‘‘
’’خودی‘‘۔ یہ مختصر سی نظم فردوسی کے ایک شعر پر تضمین ہے۔ تضمیں کے صرف دوشعر ہیں مثنوی کی شکل میں۔ اس چھوٹی سی نظم میں اقبال نے خودی کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بڑی دلکش تشبیہ استعمال کی ہے۔ خودی کو شعلہ کہا ہے اور دولت کو شرر کہہ کر یہ پیغام دیا ہے کہ دولت کے بدلے خودی نہ بیچو۔ چنگاری شعلہ کی قسمت نہیں ہو سکتی
خود کو نہ دے سیم و زرکے عوض
نہیں شعلہ دیتے شرر کے عوض
یہ کہتا ہے فردوسی دیدہ ور
عجم جس کے سُرمے سے روشن بصر
زبہر درم تندو بدخو مبا ش
تو باید کہ باشی، درم گو مباش‘‘
’’شیخِ مکتب سے‘‘۔ اس مختصر سی نظم میں اقبال نے شیخ مکتب کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی تعلیم سے نئی نسل کی روح کو جگمگا دو اور قاآ نی کا شعر تضمین کر کے یہ بتایا کہ تم روحِ انسانی کے معمار ہو۔ اگر اپنے بنائے ہوئے صحن کو روشن رکھنا چاہتے ہو تو سورج کے آگے دیوار نہ اٹھائو۔ یہ طنز ہے مکتبی ملّا کی تنگ نظری پر جن کی فرسودہ تعلیم سے نئی نسل کے ذہن ٹھٹھر جاتے ہیں
شیخِ مکتب ہے اک عمارت گر
جس کی صنعت ہے روح انسانی
نکتۂ دلپذیر تیرے لیے
کہہ گیا ہے حکیمِ قا آنی
’’پیشِ خورشید بر مکش دیوار
خواہی از صحنِ خانہ نورانی‘‘
’’ایک فلسفہ زدہ سیّد زاد ے کے نام‘‘۔ یہ نظم مشنوی کی شکل میں فارسی اشعار پر تضمین ہے۔ اس نظم میں اقبال نے فلسفہ کو زندگی کی دوری کہا ہے اور شہزادے کو یہ تلقین کی ہے کہ فلسفہ ـذوقِ عمل سے دور کر دیتا ہے۔ زندگی کو اگر محکم بنانا ہے اور خودی کو زمانے کی قید سے آزاد کرنا چاہتے ہو تو فلسفہ چھوڑ کر اس دین کو اختیار کرو جو سرِّ محمدؐ و ابراہیم ؑہے۔ اس کے بعد فارسی کے دو شعر تضمین کیے ہیں جو اقبال کی تعلیم کی نہ صرف تائید کرتے ہیں بلکہ نظم کے خاتمہ کو پُرزور اور موثر بنا دیتے ہیں
دین مسلکِ زندگی کی تقویم
دین سرِّ محمدؐ و ابراہیمؓ
’’دل درسخن ِ محمدی بند
اے پورِ علیؐ زبو علیؓ چند
چوں دیدۂ راہ بیں نداری
قاید قرشی بہ ازبخاری ‘‘
’’جاوید سے‘‘۔ اس نظم میں اقبال نے اپنے بیٹے جاوید کو نصیحت کی ہے۔ نظم تین بندوں پر مشتمل ہے اور ترکیب بند کی شکل میں ہے۔ ابتدائی دو بند کے خاتمہ پر نظامی کا شعر تضمین کیا ہے۔ اقبال کا کمال یہ ہے کہ مولانا نظامیؔ کے فارسی اشعار سے اپنے اردو اشعار کی لَے کو ہم آہنگ کر دیا ہے۔ ان کی نصیحت کا خلاصہ یہ ہے کہ مردانِ خدا کا آستانہ دربارِ شہنشاہی سے بہتر ہے۔ تیری تعلیم اگرچہ فرنگیا نہ ہے مگر تو درویش کے گھر کا چراغ ہے۔ تو اپنی خودی کی حفاظت کر۔ فارسی شعر جو تضمین کیا گیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ غافل نہ بیٹھ یہ کھیل کو دکا وقت نہیں ہے۔ کچھ ہنر دکھانے اور کام کرنے کا وقت ہے۔ دوسرے بند میں کہتے ہیں کہ شاہین کبھی چکور کا غلام نہیں ہو سکتا۔آبِ حیات اس دنیا میں ہو سکتا ہے۔ سچی پیاس کی ضرورت ہے۔ مجھے جو کچھ عزّت ملی ہے، سچ بولنے سے ملی ہے۔ عزّت اور نیک نامی اللہ کی دین ہے۔ یہ کسی کو میراث میں نہیں ملتی۔ اس نظم میں دوسرے بند کو پیوست کیا ہے نظامیؔ کے اس شعر سے
جائے کہ بزرگ بایدت بود
فرزندئی من نداردت سود
(بلند مقام حاصل کرنے کے لیے میرا بیٹا ہونا کافی نہیں ہے)
پہلے بند کی تضمین یہ ہے
دہقان اگر نہ ہوتن آساں
ہر دانہ ہے صد ہزار دانہ
’’غافل منشیں نہ وقت بازی ست
وقتِ ہنر است و کار سازی ست‘‘
دوسرے بند کی تضمین اقبال نے اس طرح کی ہے۔
اپنے نورِ نظر سے کیا خوب
فرماتے ہیں حضرت نظامیؔ
’’جائے کہ بزگ بایدت بود
فرزندئی من نداردت سود
اقبال نے اپنی نظموں میں جہاں کہیں فارسی شعر کو تضمین کیا ہے نگینے کی طرح جڑ دیا ہے بیشتر اشعار فارسی کے مشہور اساتذۂ غزل کے ہیں۔ غزل کے شعر کی رمزیت سے اقبال نے بڑا کام لیا۔ اقبال کی نظم کے اشعار سے فارسی کے شعر کا ربط ایسا مکمل ہے کہ معلوم ہوتا ہے فارسی کا شعر اسی موقع کے لیے کہا گیا تھا جہاں اقبال نے استعمال کیا ہے ۔ کہیں بھی یہ گمان نہیں گزر تا کہ تضمین برائے تضمین ہے۔
’’اسیری ‘‘کے عنوان سے ایک مختصر نظم ہے جس میں اقبال نے اپنا یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ ملک و قوم کی خاطر قومی رہنمائوں نے قید و بند کی سختیاں جھیلی ہیں۔ ایسے عظیم انسانوں کی اسیری ان کے لیے باعث فخر ہوتی ہے۔ حافظ کے شعر کے تمثیلی انداز سے اقبال کے نظریہ کی تشریح ہو جاتی ہے اور نظم کی تاثیر اور تضمین کی دلکشی بڑھ جاتی ہے
ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند
قطرۂ نیساں ہے زندانِ صدف سے ارجمند
مشکِ ازفر چیز کیا ہے، اک لہو کی بوند ہے
مُشک بن جاتی ہے ہو کر نافۂ آہو میں بند
ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت مگر
کم ہیں وہ طائر کہ ہیں دام و قفس سے بہرہ مند
’’شہپر زاغ وزغن دربندِ قید و صید نیست
ایں سعادت قسمتِ شہبازو شاہیں کردہ اند
’’دریو زۂ خلافت‘‘ بھی تین شعر کی مختصر نظم ہے۔ تحریک خلافت کی ناکامی کے بعد اقبال نے غیرتِ قومی کو بیدار کرنے کے لیے یہ نظم کہی۔ اقبال کا پیغام اس نظم میں یہ ہے کہ مسلمان اپنے خون کی قیمت دے کر بادشاہت خریدتا ہے۔بادشاہت کی بھیک نہیں مانگتا۔ اس نظم کے خاتمہ پر فارسی کے اس شعر کو تضمین کیا ہے
مرا از شکستن چناں عار ناید
کہ ازدیگراں خواستن مومیائی
(میری غیرت اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی کے لیے مومیائی بھی مانگنے کی روادار نہیں ہے)
اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے
تو احکامِ حق سے نہ کر بے وفائی
نہیں تجھ کو تاریخ سے آ گہی کیا ؟
خلافت کی کرنے لگا تو گدائی
خریدیں ہم جس کو اپنے لہوسے
مسلماں کو ہے ننگ وہ پادشائی
’’مرا ازشکست چناں عارناید
کہ از دیگراں خواستن مو میائی‘‘
’’طلوع اسلام‘‘۔ اس نظم کا شمار ان نظموں میں تو نہیں ہو سکتا جن کی بنیاد کسی فارسی شعر کی تضمین پر رکھی گئی ہے لیکن اس نظم میں اقبال نے عرفی کا ایک مصرع پہلے بند میں اور فارسی کے دو شعر آخری دو بندوں میں برجستہ انداز سے تضمین کر دیئے ہیں۔ اقبال کی اس ندرتِ ادا نے تضمین کے فن کو تخلیق کا درجہ دے دیا ہے۔ اس نظم کے پہلے بند میں مسلمانوں کی افسردگی دور کرنے کے لیے ایک ولولہ انگیز پیغام نشاطیہ انداز میں شروع کیا ہے اور جب اس شعر پر پہنچے
عطا مومن کو پھر درگاہِ حق سے ہونے والا ہے
شکوہِ تر کمانی، ذہن ہندی، نطق اعرابی
تو اچانک عرفی کا مصرع ذہن میں آیا جو اقبال کے جذبات کا بھی ترجمان تھا۔ اس پر ایک برجستہ مصرع لگا کر تضمین کا بر محل استعمال کیا ہے
اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل
نوا راتلخ ترمی زن چو ذوقِ نغمہ کم یا بی
یہی صورت آخری دوبندوں میں ہے جب اقبال نے تصور میںاسلام کے مستقبل کی روشن تصویر دیکھی اور یہ کہا ؎
پھر اُٹھی ایشیا کے دل سے چنگاری محبت کی
زمین جولانگہ اطلس قبایانِ تتاری ہے
تو بقول غالب نشاطِ تصور کی گرمی سے نغمہ سنج ہو کر اس بند کی تکمیل ،فارسی کے اس شعر کی تضمین سے کر دی۔
بیا پیدا خریدار است جانِ ناتو انے را
پس ازمدًت گذار افتاد بر ما کا روانے را
اس نظم کا آخری بند فارسی میں کہا ہے۔ یہ بند ایک خوشگوار مستقبل کی بشارت دینے والا نغمۂ بہار ہے جس میں فارسی کے ساقی ناموں کی سی سرمستی اور نشاط کی کیفیت ہے۔ ایسے اشعار کا خاتمہ حافظؔ کے ہی پرکیف شعر کا متقاضی تھا
بیاتا گل بیفشا نیم ومے درسا غراندازیم
فلک را اسقف بشگا فیم و طرحِ دیگر انداز یم
’’فلسفہ و مذہب‘‘ اس نظم میں اقبال نے اپنی اس کیفیت کی ترجمانی کی ہے کہ کس طرح ایک بیدار ذہن اور حساس دل رکھنے والا مفکر شاعر فلسفہ اور مذہب کے گہرے مطالعہ کے بعد تشکیک کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ اقبال سے پہلے غالب اس دو راہے پر آکر اپنا تجربہ اردو غزل کے اس شعر میں پیش کر چکے تھے
جاتا ہوں تھوڑی دور ہر اک رہرو کے ساتھ
پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں
اقبال بھی اس منزل پر آکر غالب کا سہارا لیتے ہیں اور غالب کی کیفیت کو اپنی کیفیت سے ہم آہنگ پاکر غالب کے شعر پر اپنی نظم کو تمام کر دیتے ہیں
یہ آفتاب کیا ہے سہپر بریں ہے کیا
سمجھا نہیں تسلسلِ شام و سحر کو میں
اپنے وطن میں ہوں کہ غریب الدًیار ہوں
ڈرتا ہوں دیکھ دیکھ کے اس دشت و درکو میں
کھُلتا نہیں مرے سفرِ زندگی کا راز
لائوں کہاں سے بندۂ صاحب نظر کو میں
حیران ہے بو علی کہ میں آیا کہاں سے ہوں
رومی یہ سو چتا ہے کہ جائوں کدھر کو میں
’’جاتا ہوں تھوڑی دور ہر اک رہرو کے ساتھ
پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں‘‘
’’نیبو لین کے مزار پر‘‘۔ اقبال نے فارسی کے جس شعر کو اس نظم میں تضمین کیا ہے۔ اس پر ایک تضمین ’’بانگِ درا‘‘میں ’’نصیحت‘‘ کے عنوان سے کر چکے ہیں۔’’ نصیحت‘‘ ایک طنز یہ نظم ہے اور اس نظم میں فارسی شعر کی رمزیت سے جو کام لیا گیا ہے اس سے مختلف انداز اس نظم میں اختیار کیا ہے۔ ایک خلًاق ذہن کی نکتہ آفرینی ایک شعر کی اشاریت کی نئی نئی تعبیر کس خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اس کے لطف کا احساس اس شعر کی دونوں تضمینوں کو سامنے رکھکر کیا جا سکتا ہے۔ اس نظم میں جوشِ کردار کی عظمت اور اہمیت جتانے کے بعد عبرت کے طور پر اقبال اس شعر کو پڑھتے ہیں
عاقبت منزلِ ماوادیٔ خاموشاں است
حالیہ غلغلہ در گنبدِ افلاک انداز
’’تاتاری کا خواب‘‘۔ اقبال نے اس نظم میں فارسی کے دوشعر دو مختلف بندوں میں تضمین کیے ہیں۔ تضمین کے فن کے کمال میں اقبال کی شاعرانہ قادرالکلامی کے ساتھ ان کی غیر معمولی حافظہ کی قوًت کو بھی دخل ہے۔ مشہور اور معروف اشعار کے علاوہ اقبال نے غیر معروف اشعار بھی تضمین کیے ہیں۔ اس میں ان کی شعوری کوشش شامل نہیں ہے۔ نظم کے موضوع کی کیفیت کے اعتبار سے جو شعر بھی حافظہ سے ابھر کر آیا اور بر محل معلوم ہوا اسے اقبال نے بے ساختہ تضمین کر دیا۔ شاعر کا نام یاد رہا تو حوالہ بھی دے دیا۔ ان شعروں سے متعلق فٹ نوٹ میں بس یہ اشارہ ملتا ہے۔(نصیرالدین طوسی نے غالباً شرح اشارات میں اسے نقل کیا ہے۔)
اس نظم کے پہلے بند میں ایک تاتاری خواب میں اپنی ملّت کی ردا کو پارہ پارہ دیکھتا ہے۔ ملت کی یہ ابتری مذہبی رہنمائوں کی گمراہی سے ہوئی ہے۔ اور قوم کی تن آسانی و عیش کوشی نے بھی یہ روزِ بد دکھا یا ہے کہ سارا ملک ہر طرف سے مصیبتوں کا شکار ہو رہا ہے۔ اس تکلیف دہ صورتِ حال کی تصویر کشی میں فارسی کے اس شعر کی رنگ آمیزی نے ناقابلِ بیان لطف واثر پیدا کر دیا۔
ہوائے تند کی موجوں میں محصور
سمر قند و بخارا کی کفِ خاک
بگردا گردِخود چند انکہ بینم
بلا انگشتری و من نگینم
(اپنے چاروں طرف دیکھتا ہوں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مصیبتوں کی انگوٹھی میں مجھے نگینہ کی طرح جڑ دیا گیا ہے)
دوسرے بند میں تیمور کی تربت سے روحِ تیمور کی آواز آئی کہ اگر تاتار کے لوگ محصور ہیں تو کیا ہوا اللہ کی تقدیر تو محصور نہیں ہے یعنی اس مصیبتوں کے حصار سے گھبرانا کیا۔ زندگی کا تقاضہ تو یہ ہے کہ انقلاب پیدا کرو اور ملک و قوم کی تقدیر بدل دو۔ اس بند کے خاتمہ کے لیے موزوں ترین شعریہی تھا
تقاصا زندگی کا کیا یہی ہے
کہ تورانی ہوتو تورانی سے مہجور ؟
’’ خودی راسوزوتا بے دیگر ے دہ
جہاں را انقلابِ دیگرے دہ‘‘
(اپنی خودی کو نئی گرمی اور نئی طاقت دے کر دنیا میں ایک اور انقلاب پیدا کرو)
’’خاقانی‘‘۔ یہ نظم صرف خاقانی کی عقیدت میں کہی گئی ہے۔ خاقانی غیر معمولی فضل و کمال کا شاعر تھا۔ اس کے قصائد میں جو زورِ تخیل اور جوش بیان ہے وہ کسی دوسرے قصیدہ نگار کو میسر نہیں ہوا۔ خاقانی کے نعتیہ قصائد میں رسول اکرمؐ سے غیر معمولی والہانہ عقیدت کا پُر خلوص اظہار ہے۔ اس کی شاعری میں غیر معمولی حکیمانہ بصیرت کی ترجمانی اقبال کی توجہ کا مرکز بنی اور خراج عقیدت کے طور پر اقبال نے اپنی نظم کے اس شعر کے بعد
وہ محرم عالمِ مکافات
اک بات میں کہہ گیا سو بات
فارسی کے اس شعر کو بے ساختہ تضمین کر دیا
خود بوئے چنیں جہاں تواں برد
کا بلیس بماند وبوالبشر مرد
’’مسعود مرحوم‘‘۔ یہ نظم مرثیہ ہے سر سید کے پوتے، جسٹس محمود کے بیٹے سر راس مسعود کا۔ مسعود مرحوم جب بھو پال میں تھے تو علامہ اقبال اکثر ان کے مہمان ہوتے۔ وہ علامہ اقبال کے قدر دان تھے اور علامہ ان کی محبت اور خلوص کے معترف۔ ضرب کلیم کے اکثر اشعار شیش محمل بھوپال میں کہے گئے ہیں۔ اس مرشیہ کے پہلے بند میں اقبال نے یہ کہنے کے بعد کہ
نہ کہہ کہ صبر میں پنہاں ہے چارۂ غم دوست
نہ کہہ کہ صبر معمّائے موت کی ہے کشود
سعدی کے اس شعر کو تضمین کیا ہے
دلے کہ عاشق و صابر بود مگر سنگ است
زعشق تابہ صبوری ہزار فرسنگ است
(جو دل عاشق بھی ہے اور صابر بھی وہ شاید پتھر ہے۔ عشق اور صبر ایک دوسرے سے ہزاروں فرسنگ کے فاصلے پر ہوتے ہیں۔)
’’ساقی نامہ‘‘ مثنوی کی شکل میں ایک طویل پیغامی نظم ہے۔ اقبال نے اس نظم میں اردو مثنوی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے حرکت اور عمل کا پیغام دیا ہے اور شاید اردو میں پہلی مرتبہ اپنے خودی کے تصوًر کو بڑے دلنشیں پیرائے میں اردو نظم کا جامہ پہنایا ہے۔ آخری بند جو خودی کی تعریف اور تشریح پر مبنی ہے فارسی کے اس شعر پر ختم ہوتا ہے
اگر یک سرِ موئے بر تر پرم
فروغ تجلًی بسوزد پرم
خودی کے ا سرار کی پر دہ کشائی کرنے کے بعد اس نظم کے خاتمہ کے لیے اس سے بہتر شعر کوئی اور نہیں ہو سکتا ۔ نعت کے اس شعر کی نئی تعبیر نے اقبال کی نظم کی تاثیر کے دائرہ کو وسیع تر کر دیا۔ تضمین کے ربط کو نمایاں کرنے کے لیے اس نظم کے صرف آخری بند کے تضمین شدہ آخری دو شعر پیش کیے جاتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے جامۂ حرفِ تنگ
حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ
فروزاں ہے سینے میں شمعِ نفس
مگر تابِ گفتار کہتی ہے بس
’’اگر یک سرِ موئے بر تر پرم
فروغ تجلّی بسوزد پرم‘‘
’’ثنائی کے مزار پر‘‘۔ اقبال نے حکیم ثنائیؔ غزنوی کے مزار پر حاضری دینے کے بعد جو اشعار کہے ان میں ثنائیؔ کے ایک مشہور قصیدے کی پیروی کی گئی ہے۔ان اشعار میں اقبال نے یہ شعر کہنے کے بعد
حضورِ حق میں اسرا فیل ؑنے میری شکایت کی
یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کرنہ دے برپا
ثنائی کا مصرع اس خوبی سے تضمین کیا ہے کہ دونوں مصرعے ایسے مربوط اور پیوست ہوگئے کہ ایک ہی شاعر کے کہے ہوئے معلوم ہوتے ہیں
ندا آئی کہ آشوبِ قیامت سے یہ کیا کم ہے
’’گرفتہ چینیاں احرام و مکّی خفتہ دربطحا‘‘
ایک مصرع کی تضمین قطعہ اور قصیدہ کی صورت میں سوداؔ کے کلام میں بھی ملتی ہے۔ اقبال نے اس روایت کو اپنی جدّتِ ادا سے تخلیق کی بلندی پر پہنچا دیا ہے۔
’’مرزا بیدل‘‘ اقبال کی ایک مختصر اور فکر انگیز نظم ہے جس میں انہوں نے وحدت الو جود کے مسئلہ کو چھیڑا ہے۔ حقیقتِ کائنات کے متعلق ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ زمین و آسمان اور یہ دشت و کہسار حقیقت میں موجود ہے یا نظر کا دھوکا ۔ صوفیائے کرام کی ایک جماعت کے مطالق یہ سب نظر کا دھوکا ہے جب کہ دوسری جماعت کے مطابق جو کچھ ہماری نظر کے سامنے ہے وہ موجود ہے اقبال نے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ،کہ حقیقت ِدنیا کا انکشاف اہلِ حکمت کے لیے دشوار رہا ہے کیوں کہ انسان کا ذہنِ رسا اُس تنگ مینا کی طرح ہے جس میں صہبا کا رنگ باہر چھلک جاتا ہے یعنی انسانی ذہن خدا اور اس کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اقبال نے اپنی اس بات کو کہنے کے لیے مرزا بیدلؔ کے اس شعر کا سہارا لیا ہے
دل اگرمی داشت وسعت بے نشاں بودایں چمن
رنگِ مے بیروں نشست ازبسکہ مینا تنگ بود
(دل اگر وسیع ہو تا تو اس چمن کا نشان نہیں ملتا۔ مینا اس قدر تنگ تھی کہ صہبا باہر چھلک آیا) مرزا بیدلؔ نے اس کائنات کو چمن سے اور اپنے دل کو مینا سے تشبیہہ دی ہے
ہے حقیقت یا مری چشمِ غلط بیں کا فساد
یہ زمیں، یہ دشت، یہ کہسار، یہ چرخِ کبود
کوئی کہتا ہے، نہیں ہے، کوئی کہتا ہے، کہ ہے
کیاخبر ! ہے یا نہیں ہے تیری دنیا کا وجود
میرزا بیدلؔ نے کس خوبی سے کھولی یہ گِرہ
اہلِ حکمت پر بہت مشکل رہی جس کی کشود
’’دل اگر می داشت وسعت بے نشاں بودایں چمن
رنگِ مے بیروں نشست ازبسکہ مینا تنگ بود‘‘
اقبال کی تضمین نگاری کا مختصر جائزہ لینے کے بعد جو بات سامنے آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اقبال نے تضمین کے فن سے بڑا کام لیا ہے۔ وہ فارسی اساتذہ کے اشعارکو بڑے قادرالکلامی کے ساتھ اپنی نظموں کے آخر میں نگینہ کی طرح جڑ دیتے اور اپنے کلام کا نچوڑ ان اشعار میں اتنی خوبصورتی اور موثر طریقے سے پیش کرتے ہیں، جس سے تضمین شدہ نظم میں ایک نئی فضا اور ایک نئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ساتھ ہی فارسی کے اشعار کو نئی معنویت اور نئے حسن بھی میسّر ہوتے ہیں۔ اقبال کے اس تخلیقی عمل سے تضمین کے فن کو ایک نئی زندگی ملی، اس کی جہت میں وسعت پیدا ہوئی، جس سے اقبال کے ہم عصر شعرا نے بھی فائدہ اٹھایا اور آئندہ بھی اس فن سے کام لیا جاتا رہے گا۔