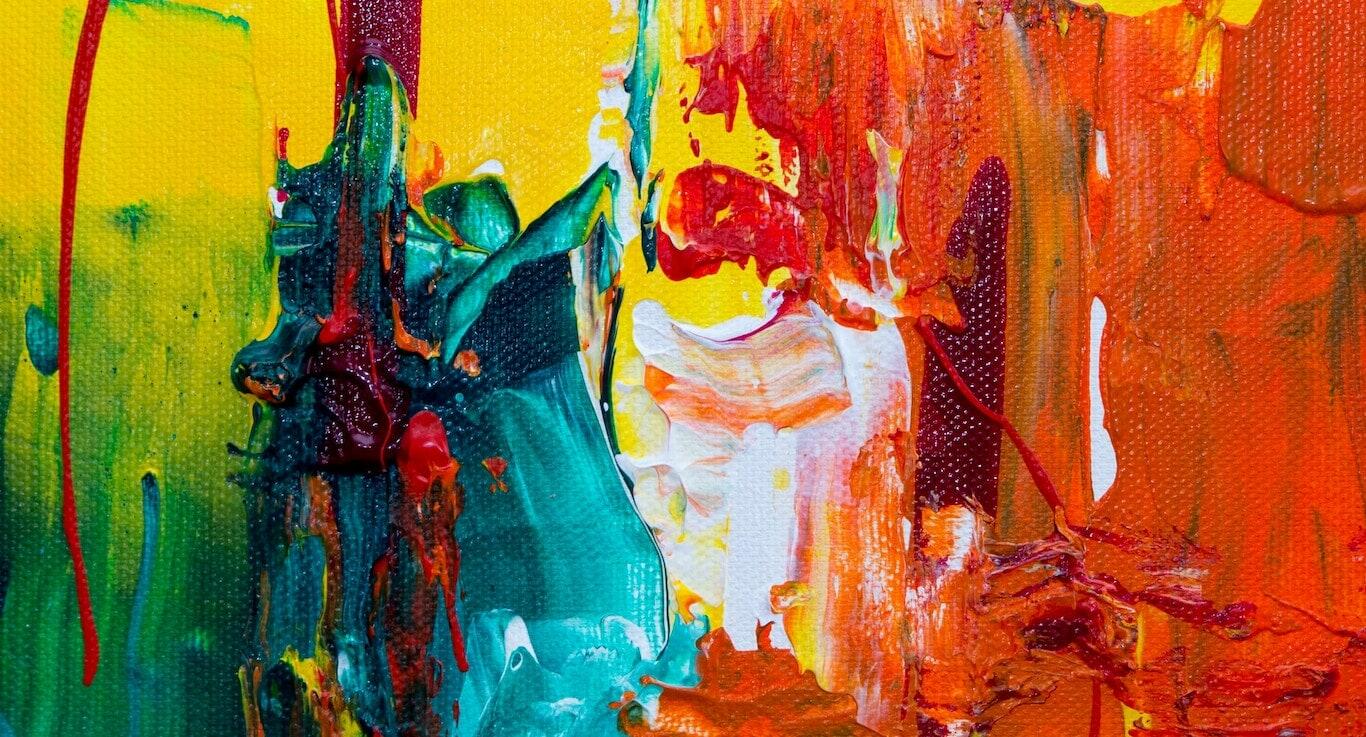اقبال کی شاعری میں فطرت کی منظر کشی
قرآن شریف میں مطالعہ کائنات سے متعلق ۷۵۶ آیتیں ہیں جو اہلِ علم کودعوتِ فکر دیتی ہیں۔موجوداتِ کائنات میں پائی جانے والی خوبیوں کاجوہر جو ناظرین میں لذت اور سرور کی خاص کیفیت پیدا کرتا ہے،دراصل حسن کہلاتا ہے اور حسن کے مظاہر کو قبول کرنے کے رجحانات انسانوں میں عموماً اور تخلیق کاروں میں خصوصاً پیدائشی طور پر پائے جاتے ہیں۔حسن کے مظاہر کو قبول کرنے کے بعد ہی تخلیق کار اشیاء کے مظہری پہلوؤں میں ایک طرح کی حقیقت سمو دینے کا کام کرتا ہے جسے فن کہا جاتا ہے۔موسیقی، نغمہ وآہنگ، رنگ آمیزی یا تصویر کشی وغیرہ کچھ ایسے فنون ہیں جو ہماری پیشہ ورانہ اور کاروباری امور اور سیاسی و اقتصادی زندگی کے فرائض کو پورا کرنے میں ہونے والی محنت اور تھکن کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں اور ہماری پریشان و مضطرب زندگی کو ایک طرح کاسکون بخشتے ہیں۔اسی لئے عظیم شاعر یا فن کار کچھ ایسی تخلیقات کو جنم دیتے ہیں جو خود ان کی حیات کی بقا کے لئے اتنی ضروری نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ایسا کرتے ہوئے انہیں مسرت ضرور ہوتی ہے۔اسی لئے ایک تخلیق کار اپنی فطری ذہانت کے سہارے ایک قسم کی شاہانہ فیاضیوں کا برملا اظہار کرتا رہتا ہے۔ان تخلیق کاروں میں علّامہ اقبال خاص اہمیت کے حامل ہیں جنہوں نے فطرت کا مطالعہ کیا ہے اور اس کے حسین مناظر کی ایسی تصویر کشی کی ہے جس کی نظیراردو ادب میں نایاب نہیں توکم یاب ضرور ہے۔اقبال کی شاعری میں مناظر فطرت کی تصویر کشی کا تجزیہ کرنے سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کائنات کیا ہے؟فطرت کسے کہتے ہیں؟کیا فطرت ِکائنات واقعی بے حد حسین ہے؟یا صرف ایک بد صورت مادہ ہے؟فطرتِ کائنات اگر حسین ہے تو پھر حسن کیا ہے؟ان تمام سوالوں کے جواب فلسفیوں اور صوفیوں نے دیے ہیں۔ مطالعۂ کائنات فلسفیوں اور صوفیوں کا اہم موضوع رہا ہے۔اس کے متعلق متعدد فلسفیوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔مثلاًلائبنیز کے فلسفۂ مونادیت کے مطابق کائنات موناد وںکا ایک بڑا مجموعہ ہے جو نہایت ہی سادہ ، ناقابلِ تقسیم اورغیر فانی ہے۔(واضح ہو کہ موناد ایک طرح کے مراکزقوت ہیں جن میں سے ہر وقت توانائی پھوٹتی رہتی ہے۔مونادوں کو روحیتی ذرّات(Spiritual Atoms) بھی کہا جاتا ہے۔لائبنیزکا یہ خیال کہ کائنات مونادوں کا مجموعہ ہے صحیح معلوم ہوتا ہے کیوں کہ اس نے مونادوں کو روحیتی ذرّات یعنی Spiritual Atomsکہا ہے جو قوت کے مراکز ہیں اور جن سے توانائی نکلتی رہتی ہے۔جدید سائنسی تھیوریزTheories) ( نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ مادے کا سب سے چھوٹا ذرّہ جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا Atom کہلاتا ہے جس کے اندر بے شمار توانائی ہوتی ہےAtomکے اندر پائے جانے والے Electron,Proton and Nitron توانائی کے سرچشمے ہیں۔لیکن لائبنیز کا یہ کہنا کہ کائنات نہایت ساد ہ ہے قابلِ قبول نہیں ہے کیوں کہ موناد اگر مراکز توانائی ہے توآفتاب کی ست رنگی روشنی، پہاڑ کی اونچی چوٹیوں سے بہتے ہوئے خوبصورت جھرنے کیا توانائی کے سرچشمے نہیں ہیں ؟ اگر ہاں تو پھر کائنات سادہ کہا ںہے۔
برکلے نے بھی فطرتِ کائنات کے متعلق اپنا جو نظر یہ پیش کیا ہے وہ درست معلوم ہوتا ہے۔وہ خارجی عالم کے وجود کو تسلیم کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ تجربہ ہمیں اشیا کی صفات کا علم فراہم کرتا ہے اورصفات صرف ہمارے نفس یا ذہن کے تصورات ہیں۔اس لئے فطرت کے متعلق وہ کہتا ہے کہ فطرت دراصل تصورات اور حسیات کا ایک نظام ہے جسے خدا کچھ خاص اصولوں کے تحت محدود اذہان میں پیدا کر دیتا ہے۔فطرتِ کائنات کے سلسلے میں وھائیٹ ہیڈ نے بھی اظہارِ خیال کرتے ہوئے لکھا ہے
’’گلاب کا پھول اپنے عطر کے لیے، بلبل اپنے سرور انگیز گیتوں کے لیے اور سورج اپنی درخشندگی کے لیے شاعرانہ تخئیل کے خوبصورت موضوعات بنتے رہے ہیں۔ مگرحقیقت تویہ ہے کہ شعرا غلط فہمی کے شکارہیں اور انھیں اپنی نظموں میں خود اپنی ذات کو موضوع داد و دہش بنانا چاہیے اور تحسین بالذات اوربالذات تشکر کے کلمات اداکرنے چاہئیں کیونکہ یہ سارا حسنِ فطرت خودفطرت میں موجود نہیں، بلکہ یہ حسن تو خودانسانی ذہن کے عمل ادراک کا کمال و اعجاز ہے کہ وہ فطرت کو اس قدرخوبصورت اورخوشنما بناکر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ فطرت بالذات توایک بوجھل ومکدر صورت حال ہے، جس میں نہ تو کوئی رنگ و آہنگ ہے اورنہ ہی کوئی عالم بو و سرور ہے۔ نہ تو فطرت کوئی شئے چشیدنی ہے اور نہ ہی یہ کوئی عالم دیدنی ہے بلکہ فطرت توبالذات ایک سریع التغیر چیز ہے جس کا کوئی سرا نہیں اورنہ ہی اس میں کوئی معنی و مفہوم ہیں۔ نہ ہی اس میں غایات ومقاصد ہیں۔‘‘
(بحوالہ قاضی قیصر الاسلام ،فلسفے کے بنیادی مسائل،ص88-89)
وھائیٹ ہیڈ کے پہلے جملے میں ہی تضاد ہے۔ایک طرف وہ کہتا ہے کہ ’’گلاب کا پھول اپنے عطر کے لیے، بلبل اپنے سرور انگیز گیتوں کے لیے اور سورج اپنی درخشندگی کے لیے شاعرانہ تخئیل کے خوبصورت موضوعات بنتے رہے ہیں۔‘‘ دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ’’ فطرت بالذات توایک بوجھل ومکدر صورت حال ہے ، جس میں نہ تو کوئی رنگ و آہنگ ہے اورنہ ہی کوئی عالم بو و سرور ہے۔ ‘‘توپھر گلاب کی خوشبو،بلبل کے سر ور انگیز گیت اور سورج کی درخشندگی کیا فطرت کے حسین مناظر نہیں ہیں؟اور اگر یہ حسین مناظر نہیں ہیں تو پھر شاعرانہ تخیل کے خوبصورت موضوعات کیسے بنتے رہے ہیں؟البتہ وھائیٹ ہیڈ کا یہ کہنا درست ہے کہ’’ یہ حسن تو خودانسانی ذہن کے عمل ادراک کا کمال و اعجاز ہے کہ وہ فطرت کو اس قدرخوبصورت اورخوشنما بناکر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔‘‘
وھائیٹ ہیڈ کے نظریے سے اتفاق کرتے ہوئے کروچے نے حسن کے موضوعی نقطۂ نظر کی تائید کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہـ
’’ حسن کلیتاً نفس یاذہن کا پیدا کردہ ہے۔ یعنی یہ کہ طبیعی اشیا بجائے خود اپنے اندر ذاتی طور پر کوئی حسن نہیں رکھتیں۔ بلکہ ان اشیا کے اندرحسن کا ادراک خود ہمارے ذہن کا اعجاز ہوا کرتاہے۔ اورانھیں ہمارا ذہن ہی حسین، قبیح اورجلیل بناتا ہے۔‘‘
(بحوالہ قاضی قیصر الاسلام ،فلسفے کے بنیادی مسائل،ص47)
حسن کے متعلق رسکن کا خیال ہے کہ ہم حسن کی حقیقت سے اس وقت واقف ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے اندر خدا کے ہر کام میں حسن وجمال کا احساس کرنے لگ جائیں۔لیکن رکسن نے حسن کو ایک جال قرار دیا ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس سے قدرت، عقل یا شعور کا شکار کرتی ہے۔حسن کے متعلق بعض ا ہلِ علم حضرات کا خیا ل ہے کہ کوئی چیز صرف اسی قدرحسین ہوتی ہے، جس قدر کہ اس چیز کو اپنی نوع کے اعتبار سے ایک خاص تناسب حسن کا درکار ہوتاہو۔ چنانچہ ہمیں مثالی حسن کا مکمل عرفان صرف اسی وقت ہوسکتاہے، جب کہ ہم فنا فی التصور ہوجائیں۔ یہ تصوّر ایک ایسا نقطۂ عروج ہے کہ جہاں تمام خواہشیں یاتمام ارادے ایک ارادئہ مطلق یا خواہش کلی میں ضم ہوکر ایک بڑے کل میں فنا ہوجاتی ہیں۔ایک بڑے شاعر کا شدّتِ احساس ایک خاص تناسب حسن والی اشیا کو دیکھنے کے بعد شدید ہو جاتا ہے یا وہ ان کے تصور میں اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں اس لئے فطرتِ کائنات انہیں بے حد حسین نظر آتی ہے اور مناظر فطرت کی حسین تصویر کشی کرنے لگتے ہیں۔
وھائیٹ ہیڈ کے برخلاف ایمرسن کا خیال ہے کہ یہ کائنات بے حد خوبصورت ہے۔ہمارے چاروں طرف سحر انگیز کیفیت کا جال سا بچھا ہوا ہے جو اپنی طرف ناظرین کو متوجہ کرتی رہتی ہے لیکن ہم دنیاوی اور کاروباری معاملات میں اس قدر الجھے رہتے ہیں کہ کائنات کا حسن ہمیں نظر نہیں آتا۔اگر ہم پھر سے اپنے بچپن میں لوٹ جائیں اور ایک بچّے کی نظر سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کائنات بے حد حسین ہے۔وہ ایک جگہ لکھتا ہے
’’ ہمارے چاروں طرف کائنات کی سحر انگیز کیفیات نے ایک جال سا بنا رکھا ہے۔اور ہم خوبصورتی کے سمندر میں گویا ڈوبے ہوئے ہیں لیکن بدقسمتی سے دنیاوی مسائل میں گرفتار ہونے کے باعث اور اپنے ماحول کا ہر روز نظارہ کرنے کی وجہ سے اس کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھیں کائنات کی رعنائیوں کے لیے اندھی ہو کر رہ گئی ہیں۔اگر ایک لمحے کے لیے ہمارا بچپن واپس آجائے تو ہمیں اڑتے ہوئے طیور ، چمکتے ہوئے تارے حیران نظروں والے پھول اور شفق کے لا مثال رنگ ایک مسحور کن ترتیب کی صورت میں نظر آئیں اور ہم فرطِ طرب سے لرز اٹھیں۔ ‘‘
(بحوالہ وزیر آغا، نظم جدید کی کروٹیں، ص – ۲۷)
اس سلسلے میں ہیگل کا خیال ہے کہ کائنات ایک عالمِ متصورہ (The world of Ideas) ہے۔اس کو ہم عالمِ فطرت کہتے ہیں۔اس کے مطابق عالمِ فطرت دراصل افکار و تصورات کا ایک عالم خارجی ہے اور عقل مطلق(یعنی خدا) اپنے آپ کو اشکالِ خارجیہ میں تبدیل کرکے ہمارے سامنے عالمِ ظاہر کے طور پر ہر وقت پیش ہوتی رہتی ہے۔ہیگل کے جدلیاتی تصورکے مطابق’’ نفس کی دنیا‘‘ یعنی مبدائے اوّل ہی اصل ہے اور مادہ نفس (یعنی مبدائے اوّل) کامظہر ہے۔ہیگل کہتا ہے کہ جدلیاتی عمل، نفس سے مادہ کی جانب نزول کرتا ہے گویا لطیف ترین تصور جب بلندی سے پستی کی طرف یا عروج سے زوال کی جانب آتا ہے تو لطیف ترین سے کثیف ترین صورت اختیار کر لیتا ہے اور یہ کثیف ترین صورت مادہ کہلاتی ہے جسے ہم عالمِ ظاہر کہتے ہیں اور جسے ہمارے حواس اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ہم اس کا ادراک کرنے لگتے ہیں۔
صوفیائے کرام کے مطابق کائنات فطرت خدا کا عین ہے۔ابنِ عربی نے اس سلسلے میں یہ آیت’’کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق‘‘(یعنی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جائوں اس لیے میں نے خلقت کو پیدا کیا)۔گویا یہ تمام کائنات اسی وجود مطلق کی ’تجلی‘ہے ۔اگر فطرتِ کائنات واقعی خدائے مطلق کی تجلّی ہے تو یہ یقیناً بے حد حسین ہے۔علامہ اقبال کا بھی خیال ہے کہ تصوف کی اصل روح یعنی کائنات میں اس کے (خدا)کے سوا کسی کا وجود حقیقی نہیں ہے اورہرشئے میں اسی کاجلوہ ہے نمایاں ہے۔ساری کائنات اس کی صفات کامظہرہے۔مندرجہ ذیل بندمیںاقبال نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیاہے۔انہوں نے پہلے شعرمیںانسان کی قوتِ گویائی اورغنچوں کی چٹک کوخداکاجلوہ قراردیاہے۔دوسرے شعرمیں چاندکوشاعرکادل اوراس کی چاندنی کودردکی کسک سے تعبیرکیا ہے۔تیسرے شعرمیں اقبال نے خداکے جلوے کی مزیدوضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان اندازگفتگوسے دھوکا کھاجاتا ہے ورنہ بلبل کا نغمہ اس کی مہک اورپھولوں کی خوشبوکواس کی چٹک سے تعبیرکیاجائے توغلط نہیں ہوگاکیوں کہ موجوداتِ کائنات میں خداہی جلوہ گر ہے۔ مختصریہ کہ ہرشے کے لئے بھلے ہی مختلف الفاظ واصطلاحات وضع کرلیے گئے ہوں لیکن حقیقت یہی ہے کہ بلبل کے نغموں میں اورپھول کی خوشبومیں بھی وہی پوشیدہ ہے۔اقبال کی نظم’’جگنو‘‘کے چند اشعارملاحظہ ہوں جن میں شاعرنے تصوف کے اسی نظریے کی وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ قدرت کے حسین مناظر کی بھی تصوریرکشی کی ہے
حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے
انسان میں وہ سخن ہے غنچے میں وہ چٹک ہے
یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا
واں چاندنی ہے جو کچھ یاں درد کی کسک ہے
اندازِگفتگو نے دھوکے دیئے ہیں ورنہ
نغمہ ہے بوئے بلبل بو پھول کی چہک ہے
کثرت میں ہوگیا ہے وحدت کا راز مخفی
جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے
اسی لئے فطرت کی منظر کشی کرتے وقت اکثر مقامات پرشاعر کا وجود فطرت میںفنا ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن فنا کے مقام سے جب واپس آتے ہیں تو ان پر یہ رازمنکشف ہو جاتا ہے کہ کائناتِ فطرت اگر ایک جسم ہے تو انسان اس کی روح ہے اس لئے اقبال انسان کی عظمت کے قائل ہوجاتے ہیں اور فلسفۂ خودی جیسے نظریے کو پیش کرتے ہیں۔
نظم ’’انسان اوربزم قدرت‘‘میں اقبال نے فلسفۂ خودی کاپیغام دیاہے اور انسان کے باطن کے نورکوصبحِ خورشیدِدرخشاں پرترجیح دی ہے لیکن صبحِ خورشیدِدرخشاں سے منوربزم معمورۂ ہستی یعنی بزمِ کائنات کی جوتصویر کشی کی ہے وہ لاجواب ہے۔ صبح ہوتے ہی آفتاب کی روشنی سے کائنات کاذرّہ ذرّہ جگمگانے لگتاہے۔خورشیدکی شعائیں جب دریاؤں پرپڑتی ہیں تو کس طرح پانی کی سطح سیمِ سیال معلوم ہوتی ہے۔آفتاب کی روشنی کا ہی یہ کمال ہے کہ باغِ بہشت میں بھی رونق آجاتی ہے۔ چاروں طرف کھلے ہوئے پھولوں کی رنگت اورتازگی ،ہرے بھرے پتے اورسرسبزمیدان اسی کی روشنی کے دم سے ہے۔ شام کے وقت آسمان میں پھیلے ہوئے شفق رنگ، کالے کالے بادلوں میں نظرآنے والی لالی، خم ِشام کی سیاہی میں لال رنگ کی آمیزش پرتوِ مہرکے دم سے ہے۔شاعرنے صبحِ خورشیدِ درخشاںسے منورکائنات کے ہرذرّے کی تصویرکشی جس طرح سے کی ہے اس سے معلوم ہوتاہے کہ کائنات واقعی خدائے واحد کاعکس ہے
صبحِ خورشیدِ درخشاں کو جو دیکھا میں نے
بزم معمورۂ ہستی سے یہ پوچھا میں نے
پرتوِ مہر کے دم سے ہے اجالا تیرا
سیمِ سیّال ہے پانی تیرے دریاؤں کا
مہر نے نور کا زیور تجھے پہنایا ہے
تیری محفل کو اسی شمع نے چمکایا ہے
گل و گلزار ترے خلد کی تصویریں ہیں
یہ سبھی سورۂ واشمس کی تفسیریں ہیں
سرخ پوشاک ہے پھولوں کی درختوں کی ہری
تیری محفل میں کوئی سبز کوئی لال پری
ہے ترے خیمۂ گردوں کی طلائی جھالر
بدلیاں لال سی آتی ہیں افق پر جو نظر
کیابھلی لگتی ہے آنکھوں کو شفق کی لالی
مئے گل رنگ خمِ شام میں تونے ڈالی
رتبہ تیرا ہے بڑا شان بڑی ہے تیری
پردۂ نور میں مستور ہے ہر شئے تیری
صبح اک گیت سراپا ہے تری سطوت کا
زیرِ خورشید نشاں تک بھی نہیں ظلمت کا
’’بانگِ درا‘‘کی نظموں میں فطرت کی منظرکشی کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ پہلی ہی نظم ’’ہمالہ‘‘ میں اقبال نے خوبصورت تشبیہات و استعارات کی مدد سے قدرت کا مطالعہ اور فطرت کے حسین مناظر کی تصویر کشی کرنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کی شاعری بھی کی ہے ۔ ہمالہ سے خطاب کرتے ہوئے اس کی جغرافیائی حالت ، عظمت ، اہمیت اور افادیت کی طرف بھی ا شارے کئے ہیں۔اس نظم کا پہلا بند ہے
اے ہمالہ! اے فصیل کشورِ ہندوستاں!
چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں
تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں
تو جواں ہے گردشِ شام و سحر کے درمیاں
اس بند کے پہلے ہی مصرعے میں ’’ فصیل کشورِ ہندوستاں‘‘کہہ کراقبال نے ہمالہ کی وسعت اور پھیلاؤ کا منظر پیش کرنے کے ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ کردیا ہے کہ ہندوستان کی وہ سرحدیں جو خشکی میں ہیں ، ہمالہ کے لمبے سلسلے سے گھِری ہوئی ہیں۔انہوںنے جب یہ کہا ہے کہ آسمان اس کی بلندی کو جھک کر چومتا ہے تو اس سے نہ صرف اس کی بلندی ظاہرہوتی ہے بلکہ زمین سے آسمان تک کا نظارہ آنکھوں میں پھرنے لگتا ہے اور ساتھ ہی زمین و آسمان کی دوری بھی مٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔اسی طرح ہمالہ کو یہ کہہ کر کہ’’ تو جواں ہے گردشِ شام و سحر کے درمیاں‘‘ اس کے مناظر کو مزید دلفریب بنا دیا ہے کیوں کہ جوانی سے زیادہ پُر کشش کوئی اور چیز نہیں ہوتی ۔ ایک دوسرے شعر میں علّامہ اقبال نے ہمالہ کا نظارہ پیش کرنے کے لیے اس کی چوٹیوں کو ثریّا سے سرگوشی کرتے ہوئے دکھایا ہے اور یہ کہا ہے کہ زمین پر ہوتے ہوئے بھی ہمالہ کا وطن آسمان ہے۔اس سے نہ صرف ہمالہ کی بلندی کا احساس ہوتا ہے بلکہ ہمالہ کی وادیوں سے چوٹیوں تک اور چوٹیوں سے تاروں کی انجمن تک کے مناظر آنکھوں میں پھرنے لگتے ہیں
چوٹیاں تیری ثریّا سے ہیں سرگرم سخن
تو زمیں پر اور پنہائے فلک تیرا وطن
برف سے ڈھکی ہوئی ہمالہ کی چوٹیوں پر آفتاب کی پہلی کرن جب پڑتی ہے تو اس کا حسن دید کے قابل ہوتا ہے۔اقبال نے اس حسین منظر کی نہ صرف تصویر کشی کی ہے بلکہ چوٹیوں کو ’ سر‘ اور برف کو دستارِ فضیلت سے تعبیر کرکے ہمالہ کی اہمیت اور بڑھا دی ہے۔
برف نے باندھی ہے دستارِ فضیلت تیرے سر
خندہ زن ہے جو کُلاہِ مہرِ عالم تاب پرخندہ زن ہے جو
اقبال نے ہمالہ کے دامن میں پائی جانے و لی کالی گھٹاؤں، چشموں اور ہوا کے جھونکوں کی بھی انتہائی خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ فطرت کے ان حسین مناظر کی تصویر کشی کرنے کے لیے شاعر نے ہمالہ کی گود میں پائے جانے و الے چشموںکے پانی کوصاف اور شفاف بتانے کے لیے اس کی سطح کو آئینہ ٔ سیّال قرار دیا ہے جس میں فطرت اپنی تصویر دیکھا کرتی ہے
چشمۂ دامن ترا آئینۂ سیّال ہے
آئینے میں جب کوئی حسینہ اپنے حسن کو دیکھتی ہے تواس کے چہرے پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہونے لگتی ہے مثلاً نپولین کی بہن پَولائن بوناپارٹ(Pauline Bonaparte) نے مرتے وقت آئینہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور جب اسے آئینہ پیش کیا گیا تو آئینہ میں دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کا شکر ہے میں اب بھی خوبصورت ہوں۔ اس لئے آئینہ دیکھنے کے بعد کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔لیکن فطرت جو انتہائی حسین ہے اس پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ اپنے حسن کو آئینے میں دیکھتی ہوگی۔اقبال کا یہ شعر
حسن آئینۂ حق، دل آئینۂ حسن
دلِ انساں کو ترا حسنِ کلامِ آئینہ
بھی اس کی تائید کرتا ہے۔اقبال نے ہمالہ کی رونق اور چمک کو ظاہر کرنے کے لیے او ر آلودگی سے پاک وہاں کی ہواؤں کی اہمیت کو بتانے کے لیے اسے ہمالہ کا رومال قرار دیا ہے
دامن موجِ ہوا جس کے لیے رومال ہے
اسی نظم کے ایک اور بند میں شاعر نے فطرت کے حسین مناظر کی تصویر اس حسن و خوبی سے کی ہے کہ پہاڑ کی وادی میں نہ صرف حرکت پیدا ہو گئی ہے بلکہ یہ محاکات کی ایک عمدہ مثال بھی ہے جس سے وہاں کے تمام مناظر آنکھوں میں رقص کرنے لگتے ہیں۔ہمالہ کی وادی میں کالی گھٹاؤں کو گھڑسوار، تیز ہوا کے جھونکوں کو گھوڑے اور بجلی کی چمک کو چابک سے تعبیر کرکے ہمالہ کی وادی کو بازی گاہ بنا دیا ہے جہاں فطرت کے عناصر ہمہ وقت مختلف کھیلوں میں مصروف رہتے ہیں۔صرف اتنا ہی نہیں شاعر نے ہوا میںاڑتی ہوئی کالی گھٹاؤں کو اس مست ہاتھی سے جس کے پاؤں میں زنجیر نہ ہو سے تشبیہہ د ے کر عجیب و غریب نظارہ پیش کیا ہے
ابر کے ہاتھوں میں رہموارِ ہوا کے واسطے
تازیانہ دے دیا برقِ سرِ کوہسار نے
اے ہمالہ کوئی بازی گاہ ہے تو بھی، جسے
دستِ قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے
ہائے کیا فرطِ طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر
فیل بے زنجیر کی صورت اُڑا جاتا ہے ابر
علامہ اقبال نے ایسے بادلوں کو فیلِ بے زنجیر کہا ہے اورپہاڑی علاقوں کو بازی گاہ یعنی کھیل کا میدان قرار دیا ہے جہاں فطرت ہاتھی اور گھوڑوں کا کھیل کھیلا کرتی ہے۔ ایک دوسرے بند میں صبح کی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اور ان جھونکوں کے اثرات سے پھولوں کی کلیوں پر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو انتہائی شاعرانہ انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کی ٹھندی ہواؤں نے کلیوں پر ایسا اثر ڈالا کہ زندگی کے نشے میں ہر پھول کی کلی جھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔زندگی کے نشے میں پھول کی کلیوں کا جھومنا انتہائی لطیف خیال ہے
جنبش موجِ نسیمِ صبح گہوارہ بنی
جھومتی ہے نشّہ ہستی میں ہر گل کی کلی
مثنوی سحر البیان کے مصنف میر حسن نے بھی ایک باغ کا منظر اس طرح کھینچا ہے
گلوں کا لبِ نہر وہ جھومنا
اسی اپنے عالم میں منھ چومنا
وہ جھک جھک کے گرنا خیابان پر
نشے کا سا عالم گلستان پر
اقبال نے پودوں اور پھولوں کی پتیوں کو زبان سے تشبیہہ دے کر ان کی خاموشی میں قوتِ گویائی پیدا کردی ہے اور تمام پھول یہ کہنے لگے ہیں کہ گلچیں کے ہاتھوں کی رسائی آج تک ان پھولوںتک نہیں ہو سکی
یوں زبانِ برگ سے گویا ہے اس کی خامشی
دست گلچیں کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی
اسی نظم کے ایک اوربند میںشاعر نے پہاڑ کی بلندی سے جو ندیاں راستے میں پڑے چٹّانوں اور پتھروں سے ٹکراتی ہوئی نیچے آتی ہیں ان کی نہ صرف خوبصورت منظر کشی کی ہے بلکہ ان ندیوں کو جنّت کی ندیوںیعنی کوثر و تسنیم سے بہتر قرار دیاہے جس میں قدرت اپنے آپ کو دیکھتی رہتی ہے کہ اس کے مناظر کس قدر حسین ہیں ساتھ ہی ان ندیوں سے نکلنے والی آواز کو موسیقی سے تعبیر کیا ہے۔ ساتھ ہی راستے کے نشیب وفراز سے ٹکراتی ہوئی اور مسلسل اپنی منزلیں طے کرتی ہوئی ندیوں سے فلسفۂ زندگی کی طرف بھی اشارہ کیاہے
آتی ہے ندّی فرازِ کوہ سے گاتی ہوئی
کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی
آئِنہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی
سنگِ رہ سے گاہ بچتی، گاہ ٹکراتی ہوئی
چھیڑتی جا اس عراقِ دل نشیں کے ساز کو
چھیڑتی جا اس عراقِ دل نشیں کے ساز کو
وادیٔ کہسارکی شام کی منظر کشی کرتے ہوئے شام میں پھیلتی ہوئی سیاہی کو اندھیری رات کے زلفِ رسا سے تعبیر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلٰیٔ شب کوئی جیتی جاگتی دلہن ہو جس نے اپنے بالوں کو کھول کر اپنے حسن میں اضافہ کر لیا ہواور اس حسین مناظر میں آبشاروں کی آواز دل کو اپنی طرف کھینچ ر ہی ہو۔شاعر نے اس پرفریب شام میں چاروں طرف چھائی ہوئی خاموشی کویہ کہہ کر
’’وہ خموشی شام کی جس پر تکلّم ہو فدا‘‘
شام کے وقت کی خاموشی کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے۔عام طور پر رات کی خاموشی کو وحشت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے لیکن اقبال نے اس کی اہمت کو justify کرنے کے لیے پیڑ پودوں اور درختوں پر چھائی ہوئی شام کی خاموشی کوفکری استغراق سے جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کی ہے
لیلیٔ شب کھولتی ہے آ کے جب زلفِ رسا
دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا
وہ خموشی شام کی جس پر تکلّم ہو فدا
وہ درختوں پر تفکر کا سماں چھایاہوا
اسی طرح غروب آفتاب کے وقت پہاڑوں پر پڑنے والے شفق رنگ اور اس سے ابھرنے والے مناظر کی تصویر کشی اقبال نے انتہائی خوبصورت انداز سے کی ہے۔
کانپتا پھرتا ہے کیا رنگِ شفق کہسارپر
خوش نما لگتا ہے یہ غازہ ترے رخسار پر
شاعر نے شعر کے پہلے مصرعے میں رنگ شفق کو کانپتے ہوئے دکھاکر عجیب و غریب منظر پیش کیا ہے اور دوسرے مصرعے میںشفق رنگ کو غازہ سے اور پہاڑ پر جمی ہوئی برف کو رخسار سے تعبیرکر نا انتہائی لطیف خیال ہے۔
اقبال نے ایک دوسری نظم ’’خفتگانِ خاک سے استفسار‘‘میں بھی شام کاایک حسین منظرپیش کیاہے جس میںمہرِروشن کوشام کے نقاب سے تشبیہ دے کر کہاہے کہ شام کے رخ سے نقاب اٹھ گیایعنی شام ہوگئی۔پھراندھیرے کوگیسوئے شام سے تعبیرکرکے شانۂ ہستی پربکھیردیاہے جس سے دنیاتاریکی میں ڈوب گئی ہے اورتمام لوگوں پرنیندکاغلبہ ہونے لگاہے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان نے لبِ گفتارپرجادوکردیاہواور ساحرشب بھی اب دیدۂ بیدارپرنظررکھے ہوئے ہے۔شاعرنے شام اورشام کے بعدچاروں طرف رفتہ رفتہ چھائی ہوئی تاریکی اورخاموشی کی وجہ یہ بتائی ہے کہ محفلِ قدر ت خورشیدکے غروب ہونے پر ماتم کررہی ہے
مہرِروشن چھپ گیااٹھی نقاب روئے شام
شانۂ ہستی پہ ہے بکھراہوا گیسوئے شام
یہ سیہ پوشی کی تیاری کسی غم میں ہے
محفلِ قدرت مگرخورشیدکے ماتم میں ہے
کر رہا ہے آسماں جادولبِ گفتار پر
ساحرِ شب کی نظرہے دیدۂ بیدار پر
اقبال نے نظم’’ ابرِ کوہسار‘‘ میں بھی فطرت کا مطالعہ پیش کیا ہے اور خوبصورت تشبیہوں اور استعاروں کی مدد سے قدرت کے حسین مناظر کی بے حد خوبصورت تصویر کھینچی ہے۔ اس نظم میںشاعر نے تمثیلی اندازِ بیان اختیار کرتے ہوئے کوہسار کے بادل کو جاندار کی صورت میں پیش کیا ہے اور بادل کی زبانی اس کی تمام خو بیوں کو بیان کیا ہے اور بادل کی وجہ سے پہاڑ کی وادیوں میں جو حسین مناظرنظر آتے ہیں ان کی تصویر کشی کی ہے۔شاعر نے یہ کہہ کر کہ ابرِ کوہسار کے دامن میں چاروں طرف پھول بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور پہاڑ کی وادیوں کے ہرے بھرے گھاس کو مخمل کے بچھونے سے تشبیہ دے کر نہ صرف پہاڑ کی وادیوں کی حسین منظر نگاری کی ہے بلکہ ابرِکوہسار کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے
ہے بلندی سے فلک بوس نشیمن میرا
ابر کہسار ہوں گل پاش ہے دامن میرا
کبھی صحرا، کبھی گلزار ہے مسکن میرا
شہر و ویرانہ مرا، بحر مرا، بن میرا
کسی وادی میں جو منظور ہو سونا مجھ کو
سبزئہ کوہ ہے مخمل کا بچھونا مجھ کو
دراصل بارش کی وجہ سے ہی کسانوں کی کھیتی اور میدانوں کے سبزے لہلہا تے ہیں۔لیکن اس بات کو کہنے کے لیے شاعر نے جو پیرایۂ بیان اختیار کیا ہے وہ قابلِ تعریف ہے
مجھ کو قدرت نے سکھایا ہے دُر افشاں ہونا
ناقۂ شاہد رحمت کا حُدی خواں ہونا
غم زدائے دلِ افسردئہ دہقاں ہونا
رونق بزمِ جوانانِ گلستاں ہونا
دُر افشاں (یعنی موتی ) بلبلے کا استعارہ بالکنایہ ہے۔ اس استعارے سے مصرعے میںجہاں حسن پیدا ہوا ہے وہیں بارش کے وقت کھیتوں اور میدانوں کا منظر آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔ اس بند کے دوسرے مصرعے میں بادل کو شاہدِ رحمت اور ناقۂ حُدی خواں سے تعبیر کر کے بادل کی آواز کو نغمہ قرار دیا گیا ہے جس کی تاثیر سے ریگستان میں اوُنٹ کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور اس طرح بادل کے گرجنے کی تصویر بھی سامنے آجاتی ہے۔اقبال کے اس بند کا یہ مصرع استعارہ بالکنایہ کی بہترین مثال ہے۔اس بند کا یہ آخری شعرقابلِ توجہ ہے
بن کے گیسو رخِ ہستی پہ بکھر جاتا ہوں
شانۂ موجۂ صرصر سے سنور جاتا ہوں
اس شعر میں شاعر نے بادل کو گیسوسے تشبیہ دے کر اس سر زمین کو خوبصورت حسینہ بنا دیا ہے اور پھر گیسو کی رعایت سے یہ کہہ کر کہ بادل’’ شانۂ موجۂ صرصر سے سنور جاتا ہے‘‘ ہوا کو حسینہ کے کندھے سے تعبیر کیا ہے جو انتہائی بلیغ ہے۔کیوں کہ ہوا کے تیز جھونکوں سے آسمان میں بادلوں کے بکھرنے اور پھر بکھر کر سنورنے کے منظر کی تصویر کشی اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں ممکن نہیں ہے۔ اقبال نے اس سرزمین کو ایک دلہن قرار دیا اور کالے کالے بادلوں کو دلہن کی زلف سے تعبیر کیا ہے جو ہوا کے جھونکوں سے دلہن کے کندھوں پر کبھی بکھر جاتی ہے تو کبھی سنور جاتی ہی۔
تیسرے بند میں بھی بادل اور بارش کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اس مضمون کو ن نئے انداز میں باندھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شاعربظاہر صرف یہ کہنا چاہتا ہے کہ بادل کہیں برستا ہے اور کہیں نہیں برستا ہے۔ لیکن جہاں برستا ہے وہاں کی نہر کو بھنور کی بالیاں پہناتا ہے۔دراصل پانی کی بوندوں سے نہر میں جو بھنور پیدا ہوتا ہے اسے شاعر نے بالیوں سے تعبیر کیا ہے ۔نہر کو گرداب کی بالیاں پہنانا صرف Poetic description ہے۔ اس مصرعے سے بھی بارش کی خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے۔شاعر آگے کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ سے بغیر برسے ہوئے بادل گزر جاتا ہے تو وہاں کے لوگ مایوس ہوجاتے ہیں اور بارش کے لیے ترسنے لگتے ہیںکیوں کہ بادل نوخیز سبزے کی امید ہے یعنی جو سبزہ ابھی ابھی زمین سے اگتا ہے وہ پانی کی کمی سے سوکھ جاتا ہے۔اس لیے اس کی زندگی کا دارومدار بارش پر ہے۔اس بند کے آخری مصرعے میں شاعر نے بادل کے بننے کی سائنسی وجوہات کی طرف روشنی ڈالی ہے۔بند ملا حظہ کیجیے
دور سے دیدئہ امید کو ترساتا ہوں
کسی بستی سے جو خاموش گزر جاتا ہوں
سیر کرتا ہوا جس دم لب جو آتا ہوں
بالیاں نہر کو گرداب کی پہناتا ہوں
سبزئہ مزرعِ نوخیز کی امّید ہوں میں
زادئہ بحر ہوں، پروردئہ خورشید ہوں میں
آخری مصرعے میں اقبال نے سائنس کے اس نقطے کو پیش کیا کہ سورج کی گرمی سے سمندر کا پانی بھاپ بن کر اُوپر اڑتا ہے یہی بھاپ جب بہت اُوپر چلی جاتی ہے تو ٹھنڈی ہو کر بادل بن جاتی ہے اور یہی بادل ہوا کا دباؤ بڑھ جانے سے برسنے لگتا ہے۔اسی لیے شاعر نے بادل کو سمندر کا بیٹا اور سورج کو پروردہ کہا ہے۔
آخری بند میں بھی شاعر نے بادل کی فضیلت کوخو بصورت انداز میں بیان کیا ہے جس سے پہاڑ ی علاقوں ،پہاڑی ندیوں، پہاڑ کے آس پاس کے میدانوں، ان میدانوں میں کھلے ہوئے پھولوں اور اس علاقے میں بنے ہوئے جھونپڑوں کا منظر آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بادل کی اہمیت کا احساس اپنے قاری کو کرا دیتا ہے۔شاعر کہتا ہے کہ پہاڑ کے جھرنوں میں سمندر جیسی جو ہلچل ہے وہ بادل نے اسے عطا کی ہے۔ شاعر نے یہ بتا کر کہ پرندے بادل کی آواز میں محو ہوجاتے ہیں،بادل کی آواز کو نغمہ قرار دے دیا ہے۔اس بند کے تیسرے مصرعے میں شاعر نے بادل کو حضرتِ عیسیٰؑ قرار دے دیا ہے یعنی جس طرح حضرت عیسیٰؑ علیہ اسلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اسی طرح بادل بھی سبزے کو ہرے بھرے ہو جانے کے لیے حکم دیتا ہے۔ شاعر آگے کہتا ہے کہ بادل صرف غنچوں کو کھلنا ہی نہیں سکھاتا بلکہ اپنی رحمت سے کسانوں کے جھونپڑوں میں وہی خوشی پیدا کردیتا ہے جو خوشی محلوں میں پائی جاتی ہے
چشمۂ کوہ کو دی شورش قلزم میں نے
اور پرندوں کو کیا محو ترنّم میں نے
سر پہ سبزہ کے کھڑے ہو کے کہا قم میں نے
غنچۂ گل کو دیا ذوقِ تبسم میں نے
فیض سے میرے نمونے ہیں شبستانوں کے
جھونپڑے دامن کہسار میں دہقانوں کے
نظم ’’کہسار‘‘میں اقبال نے ایبٹ آباد(پاکستان) کے سربن (پہاڑ)کی چوٹی کے اردگردکالی گھٹااورگھٹاسے بارش ہونے اوروادیٔ کہسار کے حسین پھولوں پرپڑی ہوئی بارش کی بوندوں کی انتہائی خوبصورت تصویرکشی کی ہے۔پہلے شعرمیں شاعر نے مشرق کی طرف سے کالی گھٹاکے آنے اور سربن پہاڑ پرچھانے کی تصویرکھینچی ہے۔کالی گھٹاکی رعایت سے سربن کے چاروں طرف چھائے ہوئے کالے کالے بادلوں کو شاعرنے سیاہ پوش ہونے سے تعبیرکیاہے۔دوسرے شعرمیں آفتاب کوکالے بادلوںمیں روپوش ہونے کانقشہ کھینچاہے اوربادلوں کوگھوڑوں سے تعبیرکیا ہے اورپھر یہ کہا کہ توسنِ ابر پرسوار ہوکر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوابھی آئی جوانتہائی خوبصورت تصویرکشی ہے ۔تیسرے شعرمیں شاعرنے گھٹاکوخاص میکدہ سے تعبیرکیا ہے جو دعوتِ مئے نوشی دیتی ہے۔چوتھے شعرمیں شاعرنے بارش کی بوندوں کوگہرسے تعبیرکرکے یہ کہاہے کہ گھٹا چمن میں قبائے گُل میں گہرٹاکنے آئی ہے جس سے چمن میں دائمی خوشی پیداہوگئی ہے۔اس شعرمیں چمن کے پھولوں کی ڈالیوں اورپتوں پر پڑی ہوئی بارش کی سفیدبوندوںکی ایسی دلکش تصویرکشی کی ہے کہ معلوم ہوتاہے سرخ پوشاک میں موتی ٹکے ہوئے ہوں ۔ پانچویں شعرمیں ہواکے جھوکوں سے بادلوں کے اٹھنے اورگھرنے اورپھربرسنے کی جوتصویرکشی کی ہے وہ لاجواب ہے۔ آخری شعرمیں کالی کالی گھٹاؤں کوعجیب و غریب خیمہ سے تعبیرکیاہے جس کے سایے تلے کوہسارکے نہالوں یعنی کوہستانی پیڑاورپودے قیام کررہے ہوں۔علامہ اقبال نے اس نظم میں فطرت کی حسین منظرکشی کی عمدہ مثال پیش کی ہے
اٹھی پھر آج وہ پورب سے کالی کالی گھٹا
سیاہ پوش ہوا پھر پہاڑ سربن کا
نہاں ہوا جو رخِ مہر زیرِ دامن ابر
ہوائے سرد بھی آئی سوار توسنِ ابر
گرج کا شور نہیں ہے خموش ہے یہ گھٹا
عجیب میکدۂ بے خروش ہے یہ گھٹا
چمن میں حکم نشاطِ مدام لائی ہے
قبائے گل میں گہر ٹانکنے کو آئی ہے
جو پھول مہر کی گرمی سے سو چلے تھے اٹھے
زمین کی گود میں جو پڑ کے سو رہے تھے اٹھے
ہوا کے زور سے اُبھرا بڑھا،اُڑا بادل
اٹھی وہ اور گھٹا لو برس پڑا بادل
عجیب خیمہ ہے کوہسار کے نہالوں کا
یہیں قیام ہو وادی میں پھرنے والوں کا
اقبال کی نظم ’’ایک آرزو‘‘جوبانگِ دراکی بہترین نظموں میں سے ایک ہے اور جس میں شاعر نے سادگی،سلاست اثرآفرینی اورشاعرانہ مصوری کے کمالات کا بہترین مظاہرہ کیاہے۔اس نظم کے مندرجہ ذیل اشعارمیںاقبال نے وادیٔ کہسار میں بہتی ہوئی ندی کے دونوں طرف لگے ہوئے ہرے ہرے بیل بوٹوں اور پانی میں ان کے عکس کی بے مثال تصویرکشی کی ہے۔ندی کے صاف پانی کوکیمرے سے تعبیرکیا ہے جوندی کے کنارے دونوں جانب فطرت کے حسین مناظرکو اپنے اندرقید کررہاہو۔شاعرنے دوسرے شعرمیںکہسار کے حسین مناظر کی دلکشی کو بیان کرنے کے لیے پانی کے موج بننے کی سائنسی وجہ کو بتانے کے بجائے یہ کہہ کرکہسارکے دلکش نظارے کودیکھنے کے لیے پانی موج بن کراُٹھ اُٹھ کردیکھتاہے ،شاعرانہ حسن پیداکردیاہے اورتمام منظر آنکھوں میں پھرنے لگتے ہیں۔ تیسرے اورچوتھے شعرمیں چاروں طرف بچھے ہوئے سبزے اور کہیں کہیں جھاڑیوں میں چمکتے ہوئے پانی کا نظرآنا اور پھولوں کی ٹہنی کوکسی حسینہ سے اورصاف پانی کو آئینہ سے تشبیہ دے کر یہ کہناکہ حسینائیں جھک جھک کر آئینہ دیکھ رہی ہیں منظرکشی کا حق اداکردیاہے اور محاکات نگاری کی عمدہ مثال بھی پیش کر دی ہے
صف باندھے دونوں جانب بوٹے بوٹے ہرے ہرے ہوں
ندّی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو
ہو دل فریب ایسا کہسار کا نظارہ
پانی بھی موج بن کراٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو
آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ
پھرپھرکے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو
پانی کوچھورہی ہوجھک جھک کے گل کی ٹہنی
جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو
اس نظم کے چنداشعاراورملاحظہ ہوں جن میں شاعر نے شام میں غروب ہوتے ہوئے سورج کوخوبصورت دلہن سے اور شام میں سورج کے رنگ کومہدی کے رنگ سے تعبیرکیاہے ۔شام میںسورج کی یہ روشنی کھلے ہوئے پھولوںپرپھیل جاتی ہے تومعلوم ہوتا ہے کہ ہرپھول سرخی لیے سنہرے رنگ کے لباس میںہے۔شام کے بعدشاعرنے رات میں چانداورتاروں،آسمان اورآسمان میں بجلی کے چمکنے کی بھی منظرکشی کی ہے جولاجواب ہے۔اشعارملاحظہ ہوں
مہدی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو
سرخی لئے سنہری ہر پھول کی قبا ہو
راتوں کوچلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم
امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو
بجلی چمک کے ان کو کٹیا مری دکھا دے
جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو
’’رات اور شاعر‘‘ایک فلسفیانہ نظم ہے جس میں اقبال نے رات اورشاعرکے درمیان ہونے والی گفتگوں سے رات کے سنّاٹے کی منظرکشی کی ہے۔اس نظم میں شاعرنے رات کے اس وقت کانقشہ کھینچاہے جب ساری دنیاسورہی ہے لیکن شاعرجاگ رہاہے۔اسے جاگتے ہوئے دیکھ کررات جگے ہونے کی وجہ دریافت کرتی ہے۔اس گفتگومیںاقبال نے چاندنی رات،گلوں کی خاموشی، پھولوں کی خوشبوکے بکھرنے کامنظر، چمکتے ہوئے تاروں کامنظر،چہارسوپھیلی ہوئی روشنی کامنظر،آسمان کی بلندی سے زمین کی پستی تک کی خاموشی،دریااوردریا کے سنّاٹے کے منظرکی تصویرکشی کرکے ایسامنظرپیش کیا جیسے ساری کائنات سورہی ہے لیکن صرف شاعرہے جس پررات کاکوئی اثرنہیں ہے
کیوں میری چاندنی میں پھرتا ہے تو پریشاں
خاموش صورتِ گل مانندِ بو پریشاں
تاروں کے موتیوں کا شاید ہے جوہری
مچھلی ہے کوئی میرے دریائے نور کی تو
یا تو مری جبیں کا تارا گرا ہوا ہے
رفعت کو چھوڑ کر جو پستی میں جا بسا ہے
خاموش ہو گیا ہے تارِ رباب ہستی
ہے میرے آئینے میں تصویرِ خوابِ ہستی
دریا کی تہ میں چشمِ گرداب سو گئی ہے
ساحل سے لگ کے موجِ بیتاب سو گئی ہے
پستی زمیں کی کیسی ہنگامہ آفریں ہے
یوں سو گئی ہے جیسے آباد ہی نہیں ہے
شاعر کا دل ہے لیکن ناآشنا سکوں سے
آزاد رہ گیا تو کیوں کر مرے فسوں سے
نظم ’’چاند اورتارے‘‘میں اقبال نے اگرچہ زندگی کے اس فلسفہ کوبیان کیاہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ زندگی عمل اورجدوجہدکانام ہے لیکن اس نظم میں شاعرنے چاند اورتاروں کی گفتگوکے ذریعہ چاندنی رات کاحسین منظرپیش کیاہے۔چاندانسانوں کی طرح ہروقت حرکت میںرہتا ہے اورزندگی کا پیغام دیتا ہے ۔ستارے بھی رات بھرچلتے ہیں صبح ہونے تک چمکتے رہتے ہیں لیکن جب صبح ہوتی ہے تب فناہوجاتے ہیں ۔ستارے یہ درس دیتے ہیں کہ دنیاکی ہر شئے ستاروں کی مانندگردش سفرمیں ہے اورکسی بھی شئے کوسکون نہیں ہے۔اس نظم کے اشعارکی مدد سے اقبال نے چاندتاروں کی دنیاکے علاوہ کائنات کی ہر شئے میں حرکت پیداکردی ہے اورآسمان سے زمین تک کی تمام اشیاکی منظرکشی کو بھی واضح انداز میں ہمارے سامنے پیش کردیا ہے
ڈرتے ڈرتے دمِ سحرسے
تارے کہنے لگے قمر سے
نظارے رہی وہی فلک پر
ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر
کام اپنا ہے صبح و شام چلنا
چلنا چلنا مدام چلنا
بے تاب ہے اس جہاں کی ہر شے
کہتے ہیں جسے سکوں نہیں ہے
رہتے ہیں ستم کشِ سفر سب
تارے انساں شجر حجر سب
ہوگا کبھی ختم یہ سفرکیا
منزل کبھی آئے گی نظر کیا
اقبال نے اپنی نظم ’’ فلسفۂ غم‘‘میں بھی نظم ’’چاند اورتارے‘‘کی طرح زندگی کے فلسفے کوبیان کیاہے۔لیکن اس نظم کے پانچویں بندمیں پہاڑکی بلندی اوراس بلندی سے آتی ہوئی ندّی ،اس کے شوراورآسمان میں اڑتے ہوئے طائروں کاحسین منظرپیش کیاہے۔ بلندی سے چٹّانوں پرپانی کے گرنے اورچاروں طرف بکھرجانے کے خوبصورت منظرکی بھی تصویر کشی کی گئی ہے۔پانی کی بوندوں کوبکھرکر ایک دوسرے سے جدا ہوجانے اور پھرکچھ دورجانے کے بعدآپس میں مل جانے یعنی زمین کی سطح پرپہنچ کرنہرکی صورت میں تبدیل ہوجانے کی انتہائی دلکش تصویرکھینچی ہے۔اس بندمیں پہاڑکی چوٹی سے گرتے ہوئے پانی کی مختلف شکلیں اوراس کے نشیب وفراز،بوندوں کے بکھرنے اورملنے پھرمل کرنہرکی صورت اختیارکرنے اورنہرکے پانی کی رفتاراورتغیانی کی جہاں خوبصورت منظرکشی کی ہے وہیں اس کی مددسے زندگی کے نشیب وفرازاورہروقت رواں دواں رہنے کاپیغام بھی دیاہے
آتی ہے ندّی جبینِ کوہ سے گاتی ہوئی
آسماں کے طائروں کو نغمہ سکھاتی ہوئی
آئینہ روشن ہے اس کا صورتِ رخسارِ حور
گر کے وادی کے چٹانوں پر یہ ہو جاتا ہے چور
نہر جو تھی اس کے گوہر پیارے پیارے بن گئے
یعنی اس افتاد سے پانی کے تارے بن گئے
جوئے سیماب رواں پھٹ کر پریشاں ہو گئی
مضطرب بوندوں کی اک دنیا نمایاں ہو گئی
ہجر ان قطروں کو لیکن وصل کی تعلیم ہے
دو قدم پر پھر وہی جُو مثل تارِ سیم ہے
ایک اصلیت میں ہے نہرِ روانِ زندگی
گر کر رفعت سے ہجوم نوعِ انساں بن گئی
پستیٔ عالم میں ملنے کو جدا ہوتے ہیں ہم
عارضی فرقت کو دائم جان کر روتے ہیں ہم
اقبال نے اپنی نظم ’’شاعر‘‘میں کوہسارسے نغمہ سرائی کرتے ہوئے میدانی علاقے میںآتی ہوئی ندی سے انسان کوہمہ وقت مصروف عمل رہنے کا پیغام دیا ہے لیکن دلکش اورموثر استعارے اورکنایے کے استعمال سے اعلیٰ درجے کی شاعرانہ شان پیداکر دی ہے اورکہسارسے میدانوں کی طرف آتی ہوئی ندیوں کی آوازکونغمہ سرائی سے تعبیرکرکے عجیب وغریب فضاپیداکی ہے جس وادیٔ کہسارکے انتہائی خوبصورت مناظرآنکھوں میں پھرنے لگتے ہیں
جوئے سرود آفریں آئی ہے کوہسار سے
پی کے شراب لالہ گوں میکدۂ بہار سے
مستِ مئے خرام کا سن تو ذرا پیام
زندہ وہی ہے کام کچھ جس کو نہیں قرار سے
پھرتی ہے وادیوں میں کیا دختر خوش خرام ابر
کرتی ہے عشق بازیاں سبزہ مرغ زار سے
جام ِ شراب کوہ کے خم کدے سے اڑاتی ہے
پست و بلند کر کے طے کھیتیوں کوجایلاتی؟ ہے
اس بندکاپہلاشعرلاجواب ہے۔شاعرنے یہ کہہ کرکہ جوندی کہسارسے آرہی ہے وہ میکدۂ بہار یعنی موسم برسات سے شرابِ لالہ گوں پی کرآرہی ہے۔شرابِ لا لہ گوں پینے کے بعد ندی کی چال میں سرمستی آنافطری اورلازمی ہے اس پرمستزادیہ کہ نغمہ سرائی کرتے ہوئے آرہی ہے جس سے وادیٔ کہسارنغمہ زن معلوم ہونے لگتی ہے۔وادیوں میں بہتی ہوئی ندی کوابرکی بیٹی سے اوراس کی روانی کوخوش خرام سے تعبیرکرکے شاعرنے ندی کی دلکشی میں اورزیادہ اضافہ کردیاہے معلوم ہوتاہے کہ ندی نہیں بلکہ کوئی حسینہ بل کھاتی ہوئی چل رہی ہے۔شاعر نے میدانی علاقوں میں پیڑپودے اور سبزہ زاروں کوفیضیاب کرنے کو ندی کی عشق بازی سے تعبیرکرکے تغزل کارنگ پیداکردیاہے جس سے نہ صرف شعرمیں حسن پیداہوا ہے بلکہ تمام وادیٔ کہسار حسن وعشق کے رنگ میں رنگی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔آخری شعرمیں شاعرنے کوہ کے خم کدے کو پہاڑپر ہونے والی بارش سے تعبیرکیاہے جومیدانی علاقوں میں کھیتوں کوسیراب کرتی ہے۔ مختصریہ اس بندمیں علامہ اقبال نے فطرت کی انتہائی حسین منظرکشی کی ہے۔
نظم ’’شعاعِ آفتاب‘‘
صبح جب میری نگہ سودائی نظارہ تھی
آسماں پر اک شعاعِ آفتاب آوارہ تھی
میں نے پوچھا اس کرن سے اے سراپا اضطراب
تیری جانِ ناشکیبا میں ہے کیسا اضطراب
تو کوئی چھوٹی سی بجلی ہے کہ جس کو آسماں
کر رہا ہے خرمنِ اقوام کی خاطر جواں
یہ تڑپ ہے یا ازل سے تیری خو ہے،کیا ہے؟
رخص ہے؟ آوارگی ہے؟ جستجو ہے، کیا ہے یہ
’’خضرِ راہ‘‘بانگِ دراکی چندبہترین نظموں میں سے ایک ہے جس میں اقبال نے مزدورطبقہ کی حمایت کی ہے اورسرمایہ داری کے خلاف آوازبلندکی ہے۔اس نظم میں شاعراورخضرکی ملاقات اورسوال وجواب کو ڈرامائی اندازمیںپیش کیاگیاہے۔پہلے بندمیں اقبال نے خضرکی ملاقات سے پہلے پس منظرکے طورپردریاکے کنارے رات کا جومنظرپیش کیا وہ انتہائی سحرانگیز ہے۔ پہلے شعرمیں شاعرکورات میں دریا کے کنارے عالمِ اضطراب میں ٹہلتے ہوئے دکھایاگیاہے۔دوسرے شعرمیں شاعرنے ساکن ہوااورساکن دریاکاایسانقشہ کھینچا ہے کہ وہاں کی پوری فضاخاموش معلوم ہونے لگتی ہے۔تیسرے شعرمیں شاعرنے کہاہے کہ دریاکی موجیں ایسی سورہی ہیںکہ معلوم ہوتاہے کہ گہوارہ میں کوئی بچہ سورہاہو۔چوتھے شعرمیں شاعرنے پرندوں کے اپنے آشیانے میںسونے اورچاندکی روشنی میں ستاروں کے ٹمٹمانے کادلفریب منظرپیش کیاہے۔پانچویں شعرمیں خضرکے بڑھاپے میں بھی نوجوانوں کی چست ودرست جسامت کانقشہ کھینچاہے۔مختصریہ کہ اس نظم کے پہلے بندمیںدریاکے ساحل پررات میںاضطراب کے عالم میں ٹہلتے ہوئے شاعراوروہاں کی پُرسکون اورسحرانگیزفضاکی جو منظرکشی کی ہے وہ قابلِ تعریف ہے
ساحلِ دریا پہ میں اک رات تھا محوِ نظر
گوشۂ دل میں چھپائے اک جہانِ اضطراب
شب سکوت افزا ہوا آسودہ دریا نرم سیر
تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویرِ آب
جیسے گہوارہ میں سو جاتا ہے طفلِ شیر خوار
موج مضطرب تھی کہیںگہرائیوںمیںمستِ خواب
رات کے افسوں سے طائر آشیاںنوں میں اسیر
انجمِ کم ضو گرفتارِ طلسمِ ماہتاب
دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پیکِ جہاں پیمانِ خضر
جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگِ شباب
کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرارِ ازل
چشم دل وا ہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب
فنی اعتبار سے ’’نمودِ صبح ‘‘ اقبال کی مشہورنظموں میں سے ایک ہے جوتمام شاعرانہ خوبیوں مثلاً تشبیہ،استعارہ،کنایہ،بندش کی چشتی،شوکتِ الفاظ ،جدّتِ ترکیب اور تخیل کی بلدپروازی سے آراستہ ہے۔اس نظم میں شاعرنے طلوع سحرکی انتہائی دلکش تصویرکھینچی ہے۔رات کے وقت آسمان میں جھلملاتے ہوئے تاروں، رفتہ رفتہ آسمان سے ان ستاروں کے غائب ہونے اورآخری ستارہ نجم سحرکے بھی غائب ہونے کامنظربے حد دلکش اندازمیں پیش کیاہے۔ستاروں کے غائب ہونے کے ساتھ صبح کے نمودارہونے کے منظرکوبھی پیش کیاگیاہے۔ طلوع آفتاب کا منظرانتہائی خوبصورت ہوتاہے جسے اقبال نے نادرتشبیہوں کی مددسے مزیدخوبصورت بنادیاہے۔صبح صادق کے وقت مندروں سے ناموس اورمسجدوں سے اذان کی آوازکی گونج بھی اس نظم میں سنائی دیتی ہے۔کوئل کی آوازسے تمام پرندوں کا بیدارہونے کانقشہ بھی شاعرنے کھینچاہے اور طائرانِ خوشاحالن؟؟ کاصبح میں نغمہ سنجی کرنے کامنظر پیش کرکے قدرت کے ترنم ریز قانونِ سحر کی طرف بھی اشارہ کردیاہے
ہورہی ہے زیرِدامانِ افق سے آشکار
صبح یعنی دخترِ دوشیزۂ لیل ونہار
پاچکا فرصت درودِ فصل انجم سے سپہر
کشت خاورمیں ہوا ہے آفتاب آئینہ کار
آسماں نے آمدِ خورشید کی پا کر خبر
محملِ پرواز شب باندھا سرِدوشِ غبار
شعلۂ خورشید گویا حاصل اس کھیتی کا ہے
بوئے تھے دہقانِ گردوں نے جو تاروں کے شرار
ہے رواں نجمِ سحر جیسے عبادت خانے سے
سب سے پیچھے جائے کوئی عابدِ شب زندہ دار
کیا سماں ہے جس طرح آہستہ آہستہ کوئی
کھینچتا ہوا میان کی ظلمت سے تیغِ آب دار
مطلعِ خورشید میں مضمر ہے یوں مضمونِ صبح
ہے تہِ دامانِ بادِ اختلاط انگیز صبح
جیسے خلوت گاہِ مینا میں شرابِ خوشگوار
شورشِ ناقوس آوازِ اذاں سے ہمکنار
جاگے کوئل کی اذاں سے طائرانِ نغمہ سنج
ہے ترنم ریز قانونِ سحرکا تارتار
شاعرنے پہلے شعرمیں صبح کودوشیزہ ٔلیل ونہاریعنی دن اوررات کی بیٹی سے تعبیرکرکے طلوعِ صبح کی دلکشی میں اضافہ کردیاہے۔ دوسرے شعرمیں شاعرنے آسمان سے تمام ستاروں کوفصل انجم سے تعبیرکیا جو غائب ہوچکے ہیں کیوں کہ آفتاب اب کشت خاور یعنی مشرق میںآئینہ کاریعنی نمودارہوچکاہے۔ تیسرے شعرمیں شاعرنے رات کے رخصت ہونے کے منظراورطلوعِ آفتا ب سے پہلے رات کی سیاہی ختم ہوتے وقت جوگردآلودفضانظرآتی ہے کی تصویرکشی انتہائی خوبصورت استعاروںکے ذریعے کی ہے۔چوتھے شعرمیں ستاروں کودہقان اورشرارکوآفتاب کے بیج سے تعبیرکرکے آسمان میں جگمگاتے ہوئے ستاروں کی تصویر کشی کی ہے۔پانچویں شعرمیں نجم سحرکی ماندپڑتی ہوئی روشنی کا بہت عمدہ نقشہ کھینچاہے۔چھٹے شعرمیں طلوع آفتاب کو میان سے چمکتے ہوئے تیغ سے تعبیرکرکے طلوع آفتاب کی عجیب وغریب تصویرکشی ہے۔ساتویں شعرمیں صبح کے ظہورکوآفتاب میںپوشیدہ ہونے کی تشبیہ شراب کا بوتل میں پوشیدہ ہونے سے دے کرندرت خیال کی بہترین مثال پیش کی ہے۔ الغرض شاعرنے انتہائی شاعرانہ اوردلکش اندازبیان میں آسمان کے ستاروں، رات کی روانگی،طلوع آفتاب،صبح کی آمد،مندرسے ناموس اورمسجد سے اذان کی آواز،کوئل کی کوک سے دوسرے پرندوں کابیدارہونااورفضامیںاپنے دلکش آوازکوبکھیرنے سے فطرت کی جوتصویرابھرتی ہے اس کی تصویرکشی شاعرنے جس طرح سے کی ہے وہ لاجواب ہے۔
اقبال کی نظم ’’ایک شام‘‘میں دریائے نیکرکے کنارے فطرت کی بے حد حسین منظرکشی کی گئی ہے۔دریائے نیکر(Neckar)جرمنی کے ایک شہر ہائیڈرل برگ میںہے ۔ قیام ہائیڈرل برگ کے دوران اقبال نے یہ نظم لکھی تھی)نظم کے مطالعہ سے معلوم ہوتاہے کہ یہ جگہ بے حدخوبصورت رہی ہوگی جس کے حسین مناظرنے علامہ کومسحورکردیاہوگااور بے ساختہ نظم کے اشعاروردزباں ہونے لگے ہوں گے۔متذکرہ اشعارمیں اقبال نے آسمان میں قمراور آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی قمرکی چاندنی،شجراوراشجارکی شاخوںکی خاموشی کا عجیب وغریب منظرپیش کیاہے۔شام میں پرندے جب اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں تووہ بھی خاموش ہوجاتے ہیں۔رات کے سنّاٹے میں درخت اورپودے بھی خاموش نظرآتے ہیں۔ایسامعلوم ہونے لگتاہے کہ فطرت ہی بے ہوش ہوکر شب کی گود میں سوگئی ہو۔دریائے نیکرکا پانی بھی سکوت اختیارکرچکاہے ۔ آسمان میں تاروں کاخاموش کارواں رواںہے لیکن خاموشی سے۔کوہ ودست ودریاسب ایسے خاموش ہیں جیسے قدرت مراقبے میں ہو۔یہاں تک کہ فطرت کی خاموشی اورسکوت میںشاعراپنے وجود کو بھی ضم کرلیتا ہے اورمناظرفطرت سے ہم آہنگ ہوجاتاہے
خاموش ہے چاندنی قمر کی
شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی
وادی کے نوافروش خاموش
کہسار کے سبزپوش خاموش
فطرت بے حوش ہو گئی ہے
آغوش میں شب کے سو گئی ہے
کچھ ایساسکوت کا فسوں ہے
نیکر کا خرام بھی سکوں ہے
تاروں کا خاموش کارواں ہے
یہ قافلہ بے درا رواں ہے
خاموش ہیں کوہ و دشت و دریا
قدرت ہے مراقبے میں گویا
اے دل تو بھی خموش ہو جا
آغوش میں غم کو لے کے سو جا
اقبال کی بیشترنظموں کے اشعارجن میں فطرت کی حسین منظرکشی کی گئی ہے ان میں محاکات نگاری کارنگ اس قدرشوخ ہے کہ فضامیں موسیقی اوررقص کی سی کیفیت پیداہوگئی ہے لیکن متذکرہ نظم ’’ایک شام‘‘میں چاروں طرف ایک عجیب وغریب تفکرانہ خاموشی کی کیفیت پیداہوئی ہے۔اقبال نے اس نظم میں زمین سے آسمان تک خاموشی کی ایسی تصویر کھینچی ہے کہ اس خاموشی پرتکلّم بھی فداہوجائے۔بقول اقبال
وہ خموشی شام کی جس پر تکلّم ہو فدا
وہ درختوں پر تفکر کا سماں چھایاہوا
سوزوگدازمیں ڈوبی ہوئی نظم’’گورستانِ شاہی‘‘اقبال کی مشہورنظموں میں سے ایک ہے۔فنی اعتبارسے یہ نظم لاجواب ہے۔شاعر نے اس نظم کے اشعارمیں موثراوردلکش تشبیہات واستعارات اوررمزوکنایات سے آراستہ کر کے منظرکشی ومرقع نگاری کا ایساجادوجگایاہے کہ اشعارگنگناتے ہوئے اور جھومتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ نظم ’’ایک شام‘‘کی طرح اقبال نے آسمان اورآسمان میں چھائے ہوئے بادل اوران بادلوں سے چھن چھن کرنظر آتے ہوئے چاندکی انتہائی خوبصورت منظرکشی کی ہے۔چہارسوپھیلی ہوئی چاندنی اور رات کے آغوش میں صبح صادق کے سوئے ہونے کا منظر کس قدردلآویز ہے۔اقبال نے صبح کے انتظارمیں درختوں پرچھائی ہوئی خاموشی کے منظرکوپیش کیا اورپھرخاموشی کوقدرت کی آوازسے تعبیرکرکے فلسفۂ فکرکاپہلوپیداکردیاہے۔ اس بندکے آخری شعرمیں خاموشی کے اندر سے زندگی کی کراہیں سنائی دے رہی ہیں
آسماں بادل کاپہلے خرقۂ دیرینہ ہے
کچھ مکدّر سا جبینِ ماہ کا آئینہ ہے
چاندنی پھیلی ہے اس نظّارۂ خاموش میں
صبح صادق سو ر ہی ہے رات کی آغوش میں
کس قدر اشجار کی حیرت فزاہے خامشی
بربطِ قدرت کی دھیمی سی نوا ہے خامشی
فطرت کی منظرکشی کے اعتبار سے اس نظم کاگیارہواں بندانتہائی خوبصورت اوردلکش ہے۔اس بندکے تمام اشعار عمدہ تشبیہات واستعارات اورکنایوں سے آراستہ ہیں۔شبنم کوصبح کے اشکوں سے گرکے رگِ گل کوموتی کی لڑی سے باندھنااورشبنم کی بوندوں میںآفتاب کی شعاعوںکے الجھنے کامنظرانتہائی لطیف ہے۔ دریاکے پانی کی سطح پرسورج کی کرنوں کی آماجگاہ کہہ کر دریاکے کنارے آفتاب کے دلکش نظارے کی منظرکشی قابلِ تعریف ہے۔اسی طرح جوئباراوربادبہارکوآئینہ قراردے کران میں صنوبراورغنچۂ گل کے عکس کی جو تصویرابھرتی ہے وہ بھی لاجواب ہے۔پھرباغ میں کوئل اوربلبلوں کے ترانوں کی گونج سے گلشن اور وادیٔ کہسارمیں زندگی کی جیتی جاگتی جوتصویرکشی کی ہے وہ کس قدرحیران کن ہے۔ لیکن بندکے آخری شعرمیں پیڑ سے گرتے ہوئے سوکھے پتوںکو بچوں کے ہاتھوں سے گرتے ہوئے رنگین کھلونے سے تعبیرکرکے شاعر نے دنیاکی بے ثباتی کا منظربھی پیش کردیاہے
ہے رگِ گل صبح کے اشکوں سے موتی کی لڑی
کوئی سورج کی کرن شبنم میں ہے الجھی ہوئی
سینۂ دریا شعاعوں کے لئے گہوارہ ہے
کس قدر پیارا لبِ جُو مہر کا نظّارہ ہے
محوِ حیرت ہے صنوبر جوئبار آئینہ ہے
غنچۂ گل کے لئے بادِ بہار آئینہ ہے
نعرۂ زن رہتی ہے کوئل باغ کے کاشانہ میں
چشمِ انساں سے نہاں پتوں کے غزلت خانہ میں
اور بلبلِ مضطرب رنگیں نوائے گلستاں
جس کے دم سے زندہ ہے گویا ہوائے گلستاں
عشق کے ہنگاموں کی اڑتی ہوئی تصویر
خامۂ قدرت کی کیسی شوخ یہ تحریر ہے
باغ میں خاموش جلسے گلستاں زادوں کے ہیں
وادیٔ کہسار میں نعرے شباں زادوں کے ہیں
زندگی سے یہ پرانا خاکداں معمور ہے
موت میں بھی زندگانی کی تڑپ مستور ہے
پتیاں پھولوں کی گرتی ہیں خزاں میں اس طرح
دست طفلِ خفتہ سے رنگیں کھلونے جس طرح
اقبال نے اپنی نظم’’بزم انجم‘‘کے پہلے بندمیں کنایے کی مددسے شام کی سیاہی کے ساتھ افق کی لالی اوررات کی خاموشی، آسمان میں چمکتے ہوئے تاروںکی انجمن کی انتہائی خوبصورت منظرکشی کی ہے۔پہلے شعرکے دوسرے مصرع میں لالے کے مارناکنایہ ہے مرادسورج نے افق کوسرخ کردیا۔ تیسرے مصرع میں سونے کازیورپہنانا کنایہ ہے یعنی آفتاب غروب کے وقت شفق کی لالی مرادہے۔ رات کی لیلیٰ خاموشی کے محمل بیٹھ کرآنا رات کی خاموشی میںتاروںکے چمکنے کامنظرانتہائی خوبصورت ہے۔آخری شعرمیں آسمان کوروزن کرنے میں تاروں کی مصروفیت اورخواب غفلت سے انسانوں کابیدار ہونا اورآسمان سے آتی ہوئی فرشتہ کی آوازکی منظرکشی جس طرح اقبال نے کی ہے قابلِ تعریف ہے
سورج نے جاتے جاتے شامِ شیہ قباکو
طشتِ اُفق سے لیکرلالے کے پھول مارے
پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور
قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے
محمل میں خامشی کے لیلائے ظلمت آئی
چمکے عروسِ شب کے موتی وہ پیارے پیارے
وہ دور رہنے والے ہنگامۂ جہاں سے
کہتاہے جن کو انساں اپنی زباں میں’’تارے‘‘
اقبال نے نظم’’ ماہِ نور‘‘میں چاندنی رات کی حسین منظرکشی کی ہے۔پہلے شعر میں چاندکو سورج کے ٹکڑے سے اور اس ٹکڑے کے عکس کو دریائے نیل میںتیرتی ہوئی کشتی سے تعبیرکیاہے ۔چاند کا خم جب مدوّر کی صورت میں تبدیل ہونے لگتا ہے تب طشت معلوم ہوتا ہے اس رعایت سے دوسرے شعرمیں شاعرنے مدوّرچاند کوطشتِ گردوںیعنی آسمان کی تشتری سے اوراس کی لالی کوخونِ ناب یعنی تازہ خون سے تشبیہ دے کرمتحیّراندازمیں پوچھتاہے کہ کیا قدرت کے نشترنے آفتاب کی فصدیعنی نس کھولی ہے؟پھرتیسرے شعرمیں پانی میں اس کے عکس کی جوتصویرکشی کی ہے وہ انتہائی بلیغ اور حسین ہے۔دائرہ نما چاند کودلہن کے کان کی بالی اورشام کودلہن سے تعبیرکیاہے اور حیرت وحسرت سے پوچھتاہے کہ کیا آسمان نے شام کی دلہن سے نیل کے پانی میں اس کی بالی چرا لی ہے یاپھرچاندی کی کوئی مچھلی تیررہی ہے؟الغرض شاعر نے دریائے نیل میںخم نمااوردائرہ چاند کے عکس کی جومنظرکشی ہے وہ لاجواب ہے
ٹوٹ کر خورشید کی کشتی ہوئی غرقابِ نیل
ایک ٹکرا تیرتا پھرتا ہے روئے آبِ نیل
طشتِ گردوں میں ٹپکتاہے شفق کاخونِ ناب
نشترِ قدرت نے کیا کھولی ہے فصدِآفتاب
چرخ نے بالی چرالی ہے عروسِ شام کی
نیل کے پانی میں یا مچھلی ہے سیمِ خام کی
اقبال کی نظم ’’چاند‘‘میں بھی چانداوردریامیںچاندکے عکس کا حسین منظرپیش کیا ہے۔شاعرنے یہ کہہ کرکہ
میرے ویرانے سے کوسوں دورہے تیراوطن
ہے مگردریائے دل تیری کشش سے موجزن
چاندنی رات اورچاندنی رات میں چاند کی کشش سے سمندرکی موجوں میں ہونے والے تلاطم کی انتہائی خوبصورت تصویرپیش کی ہے۔صرف اتناہی نہیں چاند اور ستاروں میں جو روشنی پائی جاتی ہے اسے نورِ عارضی یانورِحادث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔اس نور کونور محسوس بھی کہاجاتاہے ۔ روحِ حیوانی اور نورِ عارضی یانورِحادث یانورِ محسوس میں ایک جزوی مماثلت پائی جاتی ہے اس لیے تاریک راتوں میں بحری جانور آگ کی روشنی کی طرف لپکتے ہیں اورسمندری جانور پانی سے نکل کرچاندنی رات کے دلنشیں مناظرسے لطف اندوزہونے کے لیے باہرخشکی پر نکل آتے ہیں۔اقبال نے اس شعرمیں چاند، چاندنی رات ، سمندراورسمندری جانوروں کاپانی سے نکل کرساحل پرآنے کا منظرپیش کیاہے۔
اقبال کی مشہور نظم ’’جگنو‘‘کے تمام اشعارانتہائی خوبصورت اوردلکش تشبیہات واستعارات سے آراستہ ہیں۔نظم کے پہلے اور دوسرے بندمیں شاعر نے مناظرقدرت کی پُرکیف منظرکشی کی ہے۔جگنو ایک چھوٹاسا پتنگاہے لیکن خدانے اس کی دم میں روشنی پیداکردی ہے۔جب وہ اپنی دُم کواپنے بازوؤں میں چھپالیتاہے توتاریکی ہوجاتی ہے لیکن جب اڑتاہے تو اس کی دُم سے روشنی نکلنے لگتی ہے۔بجلی کی چکاچوندمیں نہ کہیں جگنونظرآتاہے اورآسمان میں ستارے نظرآتے ہیں لیکن گاؤں میں آج بھی اندھیری رات میں جگنوؤں کی روشنی سے چمن دمکنے لگتاہے۔دورسے دیکھنے سے معلوم ہوتاہے کہ چمن کہکشاں میں تبدیل ہوگیاہے جہاں چمکتے اوربجھتے ہوئے لاکھوں ستارے کوئی کھیل کھیل رہے ہیں جس کی وجہ سے چمن میں عجیب وغریب ہلچل پیداہوگئی ہے۔علامہ اقبال جوفطرت کے حسین مناظر کوایک بچہ کی آنکھوں سے دیکھتے اوراس کامشاہدہ ایک فلسفی کی نظرسے کرتے ہیں ، چمن میں جلتی اوربجھتی ہوئی جگنوکی روشنی کے حسین مناظرکودیکھ کرمحوِ حیرت ہوجاتے ہیں اورمتحیرہوکرکہنے لگتے ہیں کہ چمن میں جگنوچمک رہاہے یاپھولوں کی محفل میں شمع جل رہی ہے؟یا آسمان سے چل کرکوئی ستارہ آگیاہے؟یاچاندکی شعاعوں میں زندگی پیداہوگئی ہے؟یارات کی سلطنت میں دن کاسفیرآگیاہے؟یاپھرماہتاب کی پوشاک سے کوئی تکمہ(بٹن)ٹوٹ کرگرگیاہے؟یاسورج کے پیرہن میں کوئی ذرّہ چمک رہاہے یاپھرخداکے نورکی جھلک ہے جسے قدرت نے مبدائے اوّل کی خلوت سے دنیاکی انجمن میں لے آئی ہے؟ان تمام سوالوں کوقائم کرنے کے بعدشاعرنے جگنوکوچھوٹے چاندسے تعبیرکیاہے جوکبھی گہن سے باہرنکلتاہے توکبھی گہن میں واپس چلاجاتاہے۔شاعرنے جس طرح جگنوکی روشنی کومختلف النوع سرچشمۂ نورسے تعبیرکرکے نوروظلمت کے حسین مناظرکی تصویرکشی کی اس سے معلوم ہوتاہے کہ یہ کائنات ایک سایہ ہے ان بے پناہ تجلیوں کی شعاعوں کاجو نوراعلیٰ سے آتی ہیں۔آخری شعرمیں شاعرنے پروانہ اورجگنوکی خصوصیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہاہے کہ دونوں پتنگے ہیں لیکن پروانہ روشنی کاعاشق ہے اورجگنوسراپاروشنی ہے اوردونوں کی اپنی ایک انفرادیت اوراہمیت ہے
جگنوں کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں
یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں
آیاہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ
یا جان پڑگئی ہے مہتاب کی کرن میں
یاشب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا
غربت میں آکے چمکا گمنام تھا وطن میں
تکمہ کوئی گراہے مہتاب کی قبا کا
ذرّہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں
حسن قدیم کی یہ پوشیدہ اک جھلک تھی
لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں
چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی
نکلاکبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں
دوسرے بندمیں بھی اقبال نے خداکی تخلیقی شان کاذکرتے ہوئے کہاہے کہ کائنات میںکوئی بھی چیزایسی نہیں جوبیکارہوبلکہ ہرشئے میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرورہے جواس کاجوہرہے۔مثلاّ جگنوچھوٹاسا پتنگاہونے کے باوجودسراپانورہے۔پروانابے نورہے لیکن وہ روشنی کا عاشق ہے اوراس کاجزبۂ عشق ہی اس کاجوہرہے۔تمام پرندے اور چرند بے زبان ہوتے ہوئے بھی ان کی آوازمیں عجیب وغریب دکشی اوردلبری ہے۔پھول کی پتیوں کوزبان سے تعبیرکرکے یہ کہاہے کہ اس کااصل جوہراس کی خاموشی ہے۔شفق اورسحربے حدحسین ہے لیکن خدانے اس کی عمرمختصرکردی۔ہوا کاجوہراس کی رفتارہے توپانی کاجوہرموج ہے۔ الغرض کائنات کاکوئی بھی ذرّہ ایسانہیں جس میں اس کاجوہرموجود نہ ہواس لئے ہرذرّے میں خدا کے حسن کاجلوہ موجودہے اوریہ کائنات یقیناًبے حدحسین ہے۔نظم جگنوکے دوسرے بندکے اشعارملاحظہ ہوں جن میں قدرت کے حسین مناظرکی عمدہ تصویرکشی کی گئی ہے
ہرچیز کوجہاں میں قدرت نے دلبری دی
پروانہ کو تپش دی جگنو کو روشنی دی
رنگیں نوا بنایا مرغانِ بے نوا کو
گل کو زبان دے کر تعلیم خامشی دی
نظّارۂ شفق کی خوبی زوال میں تھی
چمکا کے اس پری کو ٹھوڑی سی زندگی دی
رنگیں کیا سحر کو بانکی دلہن کی صورت
پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی
سایہ دیا شجر کو پرواز دی ہوا کو
پانی کو دی روانی موجوں کو بیکلی دی
یہ امتیاز لیکن اک بات ہے ہماری
جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری
فطرت کے حسین مناظر میںدراصل خداہی کاجلوہ ہے اورکائنات اس کی صفات کا مظہرہے، ’’ہرچہ بینی ندانکہ مظہراوست‘‘اورقدرت کے اشیاو وتمام ہرحرکات وسکنات کے لئے اگرچہ الگ الگ الفاظ اوراصطلاحات وضع کرلیے گئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ’’ایں وحدت است ایک بہ تکرارآمد‘‘ یعنی نغمہ میں بھی وہی پوشیدہ ہے اورپھول کی خوشبومیں بھی وہی مخفی ہے توپھرپوری دنیا میں خلفشارکیوں برپا ہے؟ انسان حیوان سے بھی بدتر کیوں بنتا جا رہا ہے اور انسان ہی انسان کا دشمن کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ ملحق ایٹمی ہتھیاروں کے تجربے کیوں ہو رہے ہیںاورانسانیت کو تباہ و بربادکیوں کیا جا رہا ہے؟
یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو
ہر شئے میں جبکہ پنہا خاموشیٔ ازل ہو
مناظرفطرت کی منظر کشی کی اہمیت آج کے دور میں اور بھی بڑھتی جارہی ہے کیوںکہ گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی توازن بھی بگڑ تاجا رہا ہے جس سے کائنات کی بقا کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔اس لئے ایسے منصوبے بھی بنائے جا رہے ہیں جس سے کائنات کو محفو ظ رکھا جا سکے اورفطرت کے لطیف و نازک حسن کو برقرار رکھا جا سکے۔ان منصوبوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اہلِ دنیا کو پھر سے فطرت کے حسین مناظر کی طرف متوجہ کیا جائے تاکہ ان کے اندر کی درندگی ختم ہوجائے اور معصومیت پیدا ہو سکے او ر وہ بھی میر کی طرح یہ محسوس کر سکیں ـ
لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت گام
آفاق کی اس کار گہہ شیشہ گری کا
حوالہ جات
۱۔ قاضی قیصر الاسلام ، فلسفے کے بنیادی مسائل
۲۔ وزیر آغا، نظم جدید کی کروٹیں
۳۔ یوسف سلیم چشتی، شرحِ باغ درا
۴۔ علامہ اقبال، کلیاتِ اقبال
۵۔ رفیع الدین ہاشمی، اقبال شخصیت فکروفن
۶۔ اقبال سب کے لئے، فرمان فتحپوری
۷۔ نقد اقبال، میکش اکبر آبادی