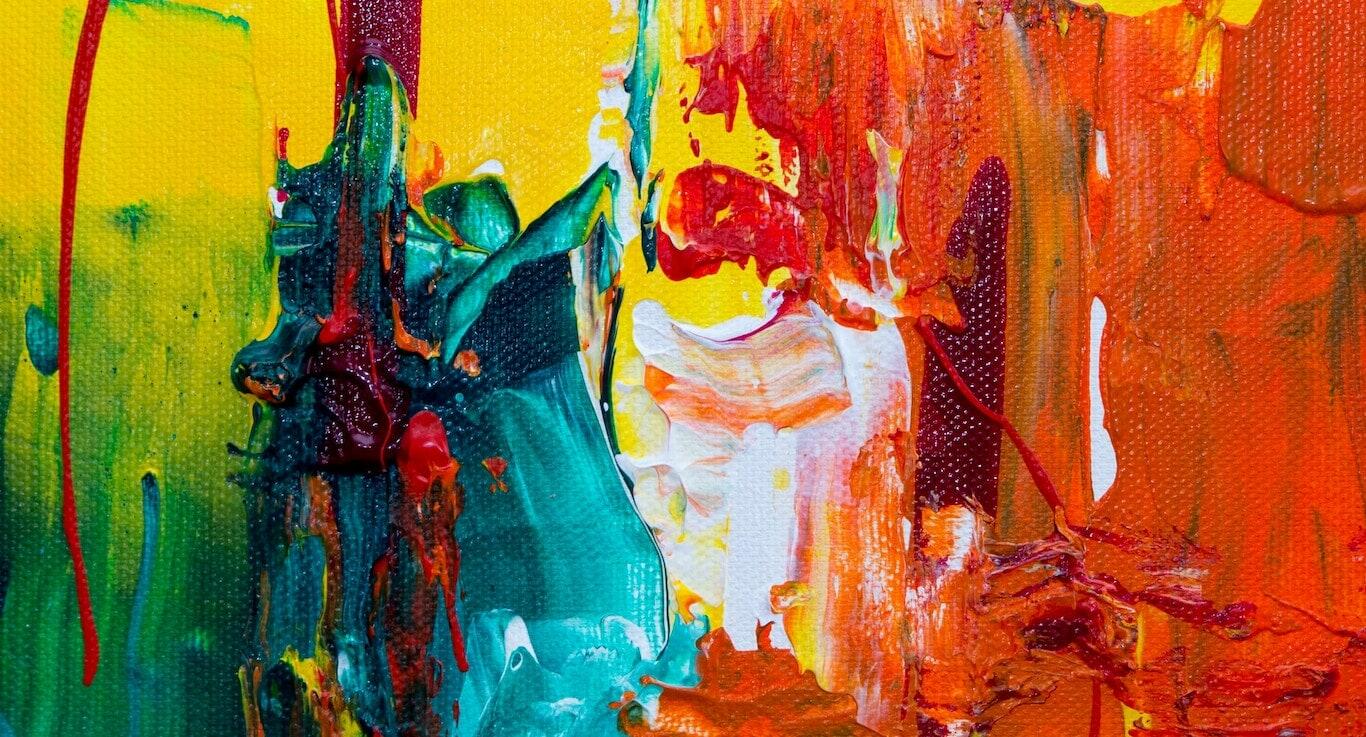غزل کے متعلق بہت کچھ لکھا گیاہے اور اب بھی لکھا جارہاہے مگر اس کا بڑا حصہ اتنا رسمی اور اس قدر یکسانیت اور یک رنگی کا شکار ہے کہ اُسے دیکھنے کا بھی جی نہیں چاہتا، پڑھنا تو دور کی بات ہے چنانچہ ڈاکٹر شیخ عقیل احمد کی تنقیدی کتاب ’’غزل کا عبوری دَور‘‘ جب مجھے ملی تو میں نے اس کے ساتھ بھی ویسی ہی بے توجہی برتی جو غزل سے متعلق تنقیدی تحریروں کے ساتھ برتتا ہوں۔ چند دنوں پہلے کسی بے کیف لمحہ میں یوں ہی ادھر ادھر سے میں نے چند صفحے پلٹے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ تنقیدی تصنیف عام ڈگر سے ذرا ہٹی ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ میں نے اسے جی لگا کر پڑھنا شروع کیا اور اس کی بعض خوبیوں سے آشنا ہوا۔
ڈاکٹرعقیل نے جس طرح دقّت نظر اور باریک بینی سے کام لے کر اس کتاب کے ذیلی ابواب قائم کیے، اس نے مجھے چونکا یا اور اپنی جانب متوجہ کیا۔ ’’انیسویں صدی کے آخر میں اردو غزل کا رنگ وآہنگ‘‘و’’اردو غزل کے مزاج میں تبدیلی کے آثار‘‘،’’غزل کی روایت سے انحراف‘‘ ،’’غزل کی کلاسیکی روایت کی تجدید اور توسیع‘‘ جیسے عنوانات اپنے آپ میں معنی خیز ہیں اور فکر ونظر کی تازگی کا احساس دلاتے ہیں۔ انھوں نے اپنے تجزیاتی مطالعہ میں اپنے عنوان اور موضوع کے ساتھ انصاف کیاہے۔ عام طور پر لوگ داغؔ، امیرؔ اور حالیؔ کے ذکر کے ساتھ انیسویں صدی کے آخری دور کے جائزہ کو مکمل سمجھتے ہیں لیکن عقیل صاحب نے منیرؔ، ظہیرؔ، مجروحؔ، سالکؔ اور جلالؔ کی غزلوں کا مطالعہ پیش کرکے صحیح معنوں میں اُس دورکی بھرپور، مکمل اور واضح تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے۔ جلال لکھنوی کی غزل گوئی خاص توجہ کی مستحق ہے۔ نیاز فتح پوری اور محمد حسن کے علاوہ کسی اہم ناقد نے ان کے کلام کو زیادہ اہمیت نہیں دی ہے۔ شیخ عقیل احمد مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انھوں نے اس طرف پوری توجہ کی اور جلال کی انفرادیت کو نمایاں کرکے اُن کے ساتھ پورا انصاف کیا۔ منیرؔ، ظہیرؔ، مجروحؔ اور سالکؔ کی غزل گوئی کو اپنے اس تنقیدی مطالعہ میں شامل کرکے انھوں نے واقعی تحقیق کا حق ادا کردیاہے۔
’’اردو غزل کے مزاج میں تبدیلی کے آثار‘‘ کے تحت انھوں نے شادؔ،صفیؔ، ثاقبؔ اور عزیزؔ کا انتخاب کرکے اپنی نظر کی گہرائی اور گیرائی کا ثبوت دیاہے۔ اُنھوں نے اشعار کے انتخاب اور اُن کے تجزیاتی مطالعہ سے واضح کردیاہے کہ ان شاعروں کے کلام میں، اس تبدیلی کے آثار دکھائی دینے لگے تھے جسے بجاطور پر مزاج کی تبدیلی کہاجاسکتاہے۔ یہاں آرزوؔ کی کمی کھٹکتی ہے آرزوؔ لکھنوی بھی اُن شاعروں میں سے تھے جن کی غزلوں کی زبان اور لہجہ میں غزل کے مزاج کی تبدیلی کے آثار بہت نمایاں طور پرنظر آتے ہیں لیکن نہ جانے کیوں عقیل صاحب اُن کو نظرانداز کربیٹھے۔ شادؔعظیم آبادی، ثاقبؔ لکھنوی اور عزیزؔ لکھنوی اُن لوگوں میں سے ہیں جن کے ذکر کے بغیر جدید اردوغزل کا کوئی مطالعہ وقیع اور سنجیدہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ ڈاکٹرعقیل نے ان کی غزل گوئی کا مفصل اور واضح تجزیہ پیش کرکے اُن کے منفرد رنگِ سخن کو نمایاں کردیاہے۔
’’غزل کی روایت سے انحراف‘‘ کے تحت انھوںنے چکبستؔ،اکبرؔالہ آبادی، محمد علی جوہرؔ، اقبالؔ اور اقبال سہیلؔ کی غزل گوئی کو خاص طور پر اپنے تنقیدی جائزہ کے لیے منتخب کیاہے۔ ان کے کلام سے روایت سے انحراف کی نشان دہی انھوں نے جس واضح اور مدلل انداز میں کی ہے اُس کی داد نہ دینا ظلم ہوگا۔ مولانا محمد علی جوہر اور اقبال سہیل کو اکثر ناقدین یا تو نظر انداز کردیتے ہیں یا سرسری گزرجاتے ہیں۔ فاضل مصنف نے عمدہ شعری انتخاب کی روشنی میں دونوں کے سیاسی رنگ کو رموزوعلائم کی روشنی میں نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اقبال سہیل تو ان غزل گو شاعروں میں سے ہیں جنھوں نے کلاسیکی روایت کی تجدید وتوسیع میں بڑا اہم کردار ادا کیاہے۔ انھوں نے اپنے اس شعر میں غلط دعویٰ نہیں کیاہے
ہوئے آزاد قیدِ آب و گل ِ اصغر بھی فانی بھی
سہیل اب کون باقی ہے قفس میں ہمزباں میرا
سہیل واقعی فانی اور اصغر کے مرتبہ کے شاعر تھے۔ ان کے کلام پر اتنی بھرپور تجزیاتی نگاہ ڈال کر شیخ عقیل احمد نے گراں قدر خدمت انجام دی ہے۔
غزل کا کلاسیکی روایت کی تجدید وتوسیع کے سلسلہ میں یگانہؔ پرانھوں نے خوب لکھاہے اور اپنے خیالات کی تائید اور موافقت میں بڑے اہم اور معتبر ناقدین کے حوالے پیش کیے ہیں جس سے ان کی رائے کو وزن، وقارملاہے۔ یاس یگانہؔ پر راہی معصوم رضا کی کتاب بہت اہم سمجھی جاتی ہے، باقر مہدی کے مضامین بھی اس ضمن میں بڑے خیال انگیز مانے جاتے ہیں۔ ان کی رائیں بھی اگر شامل ہوتیں تو کتاب کی شان میں اور زیادہ اضافہ ہوجاتا۔ اسی باب میں فراقؔ کا ذکر بھی ہونا چاہیے تھا کیونکہ نیاز فتح پوری اور مجنوں گورکھپوری جیسے ناقدین ۱۹۳۲ء کے آس پاس اُن کی غیرمعمولی اہمیت کا اعتراف کرچکے تھے اور اُن کا شمار رشیداحمد صدیقی، کلیم الدین احمد، آل احمد سرورؔ، ڈاکٹر تاثیر اور احتشام حسین نے جدید اردو غزل کے اہم ستونوں میں کیاہے۔ فیض نے اُن کو میرؔ کی روایت کا عہدجدید میں اہم ترین نمائندہ تسلیم کیاہے۔ اس لیے اُن کا ذکر جذبیؔیامجازؔ یافیضؔ کے ساتھ کسی طرح جائز اور مناسب نہیں۔ اُمید ہے کہ فاضل تنقید نگارآئندہ ایڈیشن میں اس نکتہ کو خاص طور پر ملحوظ رکھیں گے۔
اب ذرا اُس باب کی باتیں بھی ہوجائیں جس کا عنوان ’’غزل کیاہے؟‘‘ اور جس میں فاضل مقالہ نگار نے صنف غزل کی ہیئت، ارتقا، اہمیت اور قدروقیمت سے بحث کی ہے۔ اس سلسلہ میں انھوں نے رشیداحمد صدیقی، ڈاکٹریوسف حسین خان، سیّدعابد علی عابد، ڈاکٹر سیّدعبداللہ، فراق گورکھپوری اور اخترانصاری جیسے عالموں اور تنقید نگاروں کے خیالات اور افکار سے فیض اُٹھا کر جو نتائج نکالے ہیں اُن کی روشنی میں بطور ادبی صنف غزل کے حدود وامکانات کا اندازہ لگایا جاسکتاہے۔ اِس مقالہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ غزل کے بارے میں مباحث کے دروازے کھولتاہے۔ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ناقدوں اور تجزیہ نگاروں کی آرا، کو اس طرح پیش کرنا کہ اُن کے امتزاج سے ایک واضح اور ہم آہنگ تصویر اُبھر کر سامنے آئے آسان کام نہیں لیکن ڈاکٹر عقیل اس مشکل مرحلہ سے اطمینان بخش حد تک عہدہ برآہوئے ہیں۔ اتنی بات تو ماننی پڑے گی کہ غزل کی شدید مخالفت کے باوجود اور آزاد اور معریٰ نظموں کی مقبولیت کے باوجود آج بھی غزل سنجیدہ حلقوں میں بھی اپنی کشش اور مقبولیت کو قائم رکھے ہوئے ہے اور آب وتاب کے ساتھ زندہ ہے، کوئی بات تو اس صنف میں ضرور ہے جو اس کی قوتِ حیات اور بقا کی ضامن ہے۔ اسی بات اور اسی حقیقت کی تلاش کی جانب ڈاکٹر عقیل کی یہ تنقیدی تصنیف ایک جرأت مندانہ قدم ہے اور یہی اس کی اشاعت کاجواز بھی ہے۔
فاضل مقالہ نگار کا طرزِ اظہار واضح اور انداز بیان دلکش ہے۔ تضاد اور ژولیدگی سے انھوں نے اپنا دامن بچانے میں کامیابی حاصل کی ہے جو غزل کی تنقید میں ایک دشوار عمل ہے۔ صوری اعتبار سے بھی کتاب اطمینان بخش ہے۔ ساقی بک ڈپو، اُردو بازار، دہلی سے ڈیڑھ سو روپے میں مل سکتی ہے۔
ڈاکٹرمحمدمثنی رضوی
اصنافِ شعر میں جس صنف پر سب سے زیادہ لکھا گیاوہ غزل ہے یہ بھی حقیقت ہے ککہ اس صنف کی جتنی توصیف وتنقیص کی گئی شاید ہی کسی صنف کے حصے میں آئی ہو۔ زیرتبصرہ کتاب کا تعلق بھی غزل کی تنقید سے ہے، جس کے مصنف ڈاکٹرشیخ عقیل احمد ہیں اور کتاب کا نام ’’غزل کا عبوری دَور‘‘ ہے۔ دراصل یہ ان کے ایم۔فل کامقالہ ہے جو اب کتابی شکل میں شائع ہواہے— یہ کتاب پچیس سالہ(۲۵-۱۵۰۰ء) اردوغزل کی نہ صرف تاریخ ہے بلکہ اچھی تنقید کا نمونہ بھی ہے۔ یہ دور اردوغزل میں اس لیے اہمیت رکھتی ہے کہ بیسویں صدی کے شروع کے پچیس تیس سال میں اردو شاعری میں نہ صرف فکرواحساس کی سطح میں تبدیلیاں آئیں بلکہ زبان و بیان اور موضوع وہیئت میں بھی کئی تجربات کیے گئے۔ دراصل وہ دور قدیم وجدید کی کش مکش کا دور تھا۔ زندگی کی یہ کش مکش ہر سطح پر جاری تھی۔ اردو غزل بھی اس کش مکش سے دوچار تھی۔ یہ وہی زمانہ ہے جس میں بقول مصنف
’’۔۔۔۔غزل پچیس سال تک اسالیب کے تجربات کی بھٹی میں تپ کر نکھری ہے۔‘‘
یا
’’۔۔۔۔غزل کو شعرا نے اپنے خونِ جگر سے اس کو تب وتاب بخشی ہے۔‘‘
یہ کتاب تین ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں غزل کیاہے؟ کے عنوان سے غزل کے معنی ومفہوم اور تعریف بیان کی گئی ہے۔ ساتھ ہی اس کے آغاز وارتقاء اور مقبولیت کے اسباب پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ دوسرے باب میں انیسویں صدی میں غزل کے بدلتے ہوئے رنگ وآہنگ اور دبستان دہلی کی شوخی فکر اور لطافت خیال کے محروم ہوجانے کا غم نیز حالیؔ نے غزل کی اصلاح وترقی کے لیے جو کوششیں کی ہیں اسے سراہا گیا ہے ۔ اس حصے میں مجروحؔ، سالکؔ، ظہیرؔ، داغؔ، منیرؔ، امیرؔ اور جلالؔ وغیرہ کا مختصر تعارف ان کی شعری خصوصیات اور شعرا کے اشعار کا خوب صورت انتخاب بھی پیش کیا گیاہے۔ تیسرے باب کا عنوان ’’غزل کا عبوری دور‘‘ ہے۔ اس باب کے تین ضمنی حصے کیے گئے ہیں۔ پہلے حصے میں شادؔ، ثاقبؔ، صفیؔاور عزیزؔ دوسرے حصے میں چکبستؔ،اکبرؔ، اقبالؔ، محمدعلی جوہر اور اقبال سہیل۔ تیسرے حصے میں حسرتؔ، فانیؔ، اصغرؔ، جگرؔ، یگانہؔ اور میکش اکبرآبادی وغیرہ کی مختصر سوانح بیان کرکے ان کے اشعار کا صرف انتخاب ہی نہیں پیش کیا گیا ہے بلکہ اس عہد کی غزل کا تہذیبی وسماجی تناظر میں تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ اس کتاب کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ڈاکٹر عقیل نے مختلف ناقدین کی آراء کو من وعن قبول نہیں کرلیاہے بلکہ اتفاق اور استفادے کے ساتھ اختلاف بھی کیاہے اور اپنی بات کہنے کے لیے استدلالی انداز اختیارکیاہے۔ اس تحقیقی کتاب سے ایک طرف مصنف کی تلاش وجستجو کا پتا چلتاہے تو دوسری طرف ان کی تنقیدی صلاحیت کا بھی احساس ہوتاہے۔ یہ ڈاکٹر شیخ عقیل احمد کی پہلی ادبی کاوش ہے۔
اللہ کرے ذوق سفر اور زیادہ
ڈاکٹرارشادنیازی
]’’ہماری زبان‘‘۸و۱۵تادسمبر۱۹۹۶ء[
غزل کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اردو اصناف سخن میں جتنے نشیب وفراز اس نے دیکھے کسی دوسری صنف نے نہیں دیکھے۔ عادل شاہی دور کے شعراء ہاشمی، شاہی یا گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت کے تیسرے بادشاہ قلی قطب شاہ کی غزلوں کو دیکھئے تو ایسا محسوس ہوتاہے کہ غزل صرف معشوق سے ’’باتیں‘‘ کرنے تک محدود نہ تھی بلکہ محبوب کی ایک ایک ادا، ایک ایک کیفیت، نازک سے نازک تر جذبے اور احساس کی مصوری، حس پرستی، مستی وسرشاری، زیبائش وآرائش، رندمشربی غرض مے و معشوق کے حوالے سے زندگی کے سارے معاملات غزل کے موضوعات اور اس کی شناخت تھے۔ یہ ذکر اردوشاعری کے اس دور کا ہے جب اس نے ابھی چلنا ہی سیکھا تھا۔ دوشیزگی میں تو اس آہوئے رم خوردہ کی وحشت کھونی مشکل ہوگئی۔ پھر رفتہ رفتہ غم جاناں پر غم ایام حاوی ہونے لگا لہٰذا غزل میں حسن وعشق اور لطف وانبساط کی باتیں اور سوزوگداز، اثر آفرینی، رنگینی ودلکشی تو رہی لیکن اس کے ساتھ عصری تقاضوں کے تحت مختلف موضوعات جگہ پانے لگے۔ حد یہ ہے کہ سیاسی نشیب وفراز، کھردرے معاملات اور سماجی وعوامی مسائل غزل کے محبوب موضوع بنتے چلے گئے۔ غزل کے موضوعات میں اس تنوع اور وسعت کا ایک سبب اس کا اپنا مزاج بھی ہے۔ اس صنف میں اتنی گنجائش ہے کہ کسی بھی موـضوع اور مسئلے کو محض ایک شعر میں بیان کیا جاسکتاہے۔‘‘ تنگنائے غزل کا شکوہ شاعرانہ حسن طلب یا حسن ادا ہی ہے ورنہ اس میں بیان کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ شرط قدرت اظہار اور تفکر وتخیل ہے۔
غزل کو تبدیلیوں کے اس سفر میں کئی مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ یہ قدیم یا کلاسیکی دور سے جست لگاکر یک لخت جدید دور میںداخل نہیں ہوئی بلکہ اس میں بتدریج تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ تجربات وتبدیلیوں کے اسی دور کو ڈاکٹرشیخ عقیل احمد نے غزل کے عبوری دور کا نام دیاہے۔ گو کہ اس عبوری دور کے بیشتر شعراء پر الگ الگ لکھا جاتارہاہے لیکن ڈاکٹر عقیل نے ان سبھوں کو ایک جگہ سمیٹ کر اپنے دلائل اور مثالوں سے ان میں ایک ربط پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔
زیرنظر کتاب’’غزل کا عبوری دور‘‘ تین ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں غزل کی ہیئت اس کی امتیازی خصوصیات اور اس کی مقبولیت پر گفتگو کرنے کے بعد مختصر طور پر اردو غزل کے مختلف ادوار کا ایک جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اردو وغزل اپنے اتبدائی دور سے ۱۸۵۰ء تک مختلف تبدیلیوں سے آشناہوئی۔ اس ضمن میں میرؔ، سوداؔ، اور انشاؔ ومصحفیؔ کا ذکر کیاگیا ہے۔1800 سے1850 ء تک کے عہد کو اس لیے اہم قرار دیاگیا ہے کہ اسی عہد میں دہلی اور لکھنؤ اسکول قائم ہوئے۔ ۱۸۵۰ء کے بعد غزل میں داغؔ دہلوی کا رنگ تیزی سے مقبول ہوا مگر اس دور میں’’ غزل نے اپنی وہ بلندی، لطافت اور ہمہ گیری کھودی جو عہد غالب ومومن میں اس کا طرئہ امتیاز تھی۔‘‘ دوسرے باب میں دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے ان نمائندہ شعرا کے کلام کا جائزہ لیا گیا ہے جو غزل کی قدیم روایت کے امین تھے۔ ان میں داغؔ، امیرؔ، منیرؔ، ظہیرؔ، سالکؔ، جلالؔ اور حالیؔ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تیسرا باب بنیادی طور پر غزل کے عبوری دور کا باب ہے جسے مصنف نے تین ضمنی ابواب پر تقسیم کیاہے اول ’’اردوغزل کے مزاج میں تبدیلی کے آثار‘‘ جس میںشادؔ، صفیؔ،ثاقبؔ اور عزیز کا ذکر ہے۔ دوم ’’غزل کی روایت سے انحراف‘‘ اس باب میں چکسبتؔ، اکبرآبادی، محمدعلی جوہر،اقبال، سہیل اورعلامہ اقبال کی غزلوں کا جائزہ لیاگیاہے۔ سوم ’’غزل کی کلاسیکی روایت کی تجدید اورتوسیع ہے۔ اس حصے میں حسرتؔ،حالیؔ، اصغرؔ،جگرؔ، یگانہؔ، اور میکش اکبرآبادی کوموضوع بحث بنایاگیاہے ان ابواب کے بعد مصنف نے غیرمعمولی طور پر مختصر ’’خلاصہ بحث ونتائج‘‘ میں لکھا ہے کہ بیسویں صدی میں جسے جدید غزل کہا گیا وہ اچانک منظر عام پر نہیں آئی۔ زبان اور موضوع کے اعتبار سے مختلف تجزیوں سے گزرنے کے بعد۔۔۔۔ روایت کے اس انحراف سے غزل کے موضوع میں تنوع اور وسعت پیدا ہوئی۔۔۔ غزل کا عبوری دور اس کی نئی منزل کا نشانِ راہ ہے۔‘‘
کتاب پر استاد محترم ڈاکٹر مغیث الدین فریدی صاحب کا پیش لفظ ہے۔ ڈاکٹر فریدی نہ صرف اعلیٰ پائے کے شاعر، مستند استاد اور تاریخ گوئی میں اپنی مثال آپ ہیں بلکہ فن شاعری کے ماہر اور اپنے عہد کے شعبۂ اردو دہلی یونیورسٹی کے سب سے زیادہ ہردلعزیز استاد ہیں۔ انھوںنے غزل کے عبوری دور پر اپنے پیش لفظ میں ڈاکٹر شیخ عقیل احمد کی محنت اور تحقیق کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے
’’مقالہ نگار نے ان تمام مستند اور معتبر اکتسابات سے حاصل کی ہیں جنھوں نے ان شعرا کو اپنی تنقید نگاروں کے فیصلوں میں تضاد پایا جاتاہے اس لیے ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے بڑی احتیاط سے ان متضاد نظریات پر محاکمہ کیاہے اور قدیم رنگ اور جدید رنگ کی نشاندہی کرکے جس شاعر کا جتنا اور جیسا عمل رہاہے اسے معروضی انداز میں پیش کردیاہے۔‘‘
میں ڈاکٹر عقیل کو ان کی پہلی ادبی کاوش پر مبارکباد دیتاہوں اور امید کرتاہوں کہ وہ خوب سے خوب تر کی طرف اپنا یہ سفر جاری رکھیں گے۔
]قومی آواز،۸؍ستمبر۲۰۰۳ء[